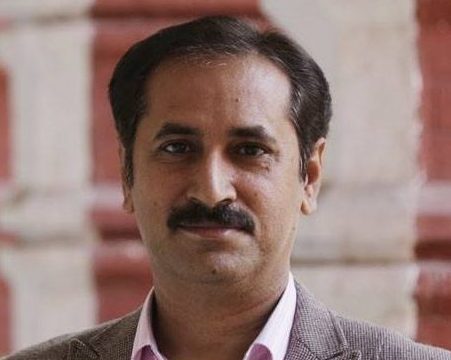نجیبہ عارف
۲۰۰۸ میں جب میں پہلی بار فرینکفرٹ آئی تھی تو اس شہر نے مجھ پر بہت گہرا اثر کیا تھا۔ تب میں نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا:
’’دوپہر کا ایک بجا ہے۔ فرینکفرٹ بادلوں کی دبیز تہ میں لپٹا ہوا ہے۔امارات ائر کا جہاز بادلوں کے غلاف کو چیرتا ہوا زمین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آہستہ سے اس نے زمین کی سطح پر پاؤں رکھا اور جیسے دھندمیں تیرنے لگا۔
یورپ کی سر زمین پر پہلا قدم۔
نجانے کتنے قافلے اس راہ سے گزرے ہوں گے لیکن نہ کہیں بجھی ہوئی آگ کا دھواں ہے نہ ٹوٹی ہوئی طناب کا نشاں۔
بیتی ہوئی صدیوں کے ہیولے پھر بھی میرے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔
سرخ ڈھلوان چھتوں والے مکانوں کے جھنڈ کسی بھولے ہوئے خواب کے نقش بناتے محسوس ہوتے ہیں۔
نظر کسی اور منظر کی متلاشی ہے۔
دل کسی اور لے پر دھڑک رہا ہے۔
وقت کے دھندلے شیشے کے آر پار دیکھنے کی خواہش کبھی کبھی کتنی شدید ہو جاتی ہے۔
اس ہلکی بھوری اور سرمئی زمین نے کتنے لعل و گہر اگلے ہیں۔
کیا تاثیرہے اس مٹی کی، اس ہوا کی اس پانی کی؟
جی چاہتا ہے اسے چکھ کر، چھو کر اور پی کر دیکھوں لیکن ایسے سوالوں کے جواب حواس کب دے سکتے ہیں۔
تو پھر کہاں سے آتے ہیں یہ جواب؟ افلاک سے تو اب سنا ہے صرف عذاب آتے ہیں۔
پھر کسی جغرافیائی خطّے کی مردم خیزی کو کوئی کیسے جی کر دیکھے۔
یہ جاننا تو شاید آسان ہے کہ کسی خاص زمین کے پھل زیادہ میٹھے کیوں ہوتے ہیں۔
مگر یہ سمجھنا کس قدر مشکل ہے کہ اتنے بے شمار فن کار، فلسفی، دانش ور اور عظیم الشان تحریکوں کے محرک کسی ایک علاقے سے کیوں جنم لیتے ہیں اور وہ بھی کسی ایک زمانے میں نہیں ، مختلف ادوار اور مختلف زمانوں میں۔ گوئٹے، شلر، کانٹ، نطشے، شوپنہار، مارٹن لوتھر، فرائیڈ، کارل مارکس، اینگلز، ہرمن ہیسے، ہانمن، یہ چند نام تو یونہی بیٹھے بٹھائے یاد آگئے بغیر کسی دقت اور کوشش کے۔ ذراسوچنے لگو تو چراغوں کی قطاریں سی جھلملانے لگتی ہیں۔ جیسے تاروں بھرا آسمان ہو۔ ایسے ستارے میری زمین سے کب پھوٹیں گے؟ میرا گھر کب جگمگائے گا؟
اور پھر ایک خاموشی، ایک خلا۔۔۔۔
اب کبھی دوبارہ جرمنی آتے ہوئے، بلکہ یورپ کے کسی بھی ملک کی سرزمین پر اترتے ہوئے ،دل میں ایسی سنسنی محسوس نہیں ہو گی۔ ایک اور پہلا تجربہ خرچ ہو گیا۔ یہ ایسا خرچ ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہوتی۔ زندگی اپنا نیا پن دھیرے دھیرے کھو دیتی ہے، مانوسیت کتنی بوجھل اور بیزارکن ہوتی ہے۔ عمر کے ایک حصے میں تو یہ خارج سے امڈ کر انسان کی طبیعت اور مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر نئے منظر بھی پرانے، متوقع اور بے معنی لگتے ہیں۔ اس عمر کی دہلیز پرکھڑے ہو کر اگر ایک بار پھر کسی سنسنی کو چھو لیا تو غنیمت ہے۔
امیگریشن کا مرحلہ اس قدر جلد اور سہولت سے طے ہو گیا کہ حیرانی ہوئی۔ ایک صاف ستھرا اور پرسکون سا ہوائی اڈہ۔ نہ کوئی بھاگ دوڑ، نہ دھکم پیل۔ نہ لمی لمبی قطاریں ، نہ انتظار کی طویل گھڑیاں، خوشگوار سا احساس ہوا۔
جولائی کا آخری ہفتہ شروع ہو رہا ہے۔سنہری دھوپ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ میں تو میزبانوں کی ہدایت کے مطابق کم از کم بارہ اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سولہ ڈگری درجۂ حرارت سے نمٹنے کے لیے تیار ہو کر آئی تھی ۔ یہاں درجہ حرارت تیس کی حد پار کر رہا تھا۔ جونہی ہم گاڑی میں سوار ہوئے، موسم کے تیور کھل کر سامنے آگئے۔ پسینے میں بھیگے ہوئے طارق کا کہنا تھا کہ ایسا موسم جرمنی میں کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ویسے تو اب دنیا بھر میں موسموں کے رنگ ڈھنگ بدل رہے ہیں۔ کرۂ ارض سورج کے نشتروں کی زد میں ہے اور انسان اپنے ناخن تدبیر سے اپنا ہی سر کھجائے جاتا ہے۔ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات جسے وہ تسخیر کے زعم میں پامال کرتا چلا جارہاتھا اب پلٹ کر انتقام پر اتر آئی ہے۔ اس کا وار سہنے کی کتنی ہمت ہے، ابھی یہ دیکھنا باقی ہے اور بند گاڑی میں حبس سے دم گھٹا جاتا ہے۔ اتنی تیز رفتار ی کے دوران گاڑی کے شیشے کھولنا بھی ممکن نہیں اور سورج کے نیزے ہر مسام میں اتر رہے ہیں۔
فرینکفرٹ شہر خیال سے خاصا مختلف نکلا۔میں تو سمجھے بیٹھی تھی، اتنا پرانا شہر ہے، گنجان اور ہنگامہ پرور ہو گا مگر یہاں تو قصہ ہی دوسرا نکلا۔ شہر کے ماحول میں ایک ٹھہراؤ، ایک دھیما پن، ایک تحمل ہے، گاڑیوں کی رفتار تیز ہے مگر ایک دوسرے کو کچل ڈالنے کے عزائم شہروں کی فضا میں جو عفونت پھیلا دیتے ہیں، وہ کہیں نہیں۔ پتھروں کی بنی سڑکوں پر چلتی ہوئی جدید ترین گاڑیاں قدیم و جدید کا ایک ایسا امتزاج اور ہم آہنگی پیش کر رہی تھیں کہ ان سے ڈر نہیں لگا، مرعوبیت کا احساس نہیں ہوا، اجنبیت کی بے مہری نہیں چبھی، ایک ہلکی ہلکی سی اپنائیت کی نرمی ارد گرد منڈلاتی نظر آئی۔ چلو اپنائیت نہ سہی مگر غیریت بھی نہیں تھی۔
ماموں سلیم اور سعیدہ باجی کا گھر شہر کے مرکز میں ہے۔ یہ اس تاریخی شہر کا سب سے زیادہ تاریخی علاقہ ہے۔ دریائے مائن کے کنارے آباد یہ بستی کئی ہزار برس قبل بھی حضرت انسان کا مسکن تھی۔ کون کہ سکتا ہے کہ اس وقت ان پتھروں پر چلنے والے، ان دریاؤں میں کشتیاں چلانے والے لوگ کون تھے، کیسے تھے، کہاں چلے گئے ۔ یورپ کے دریا بالکل پالتو جانوروں کی طرح نرم خو، بے ضرر اور حلیم الطبع معلوم ہوتے ہیں۔ شہروں کے عین بیچ میں آرام سے لیٹے رہتے ہیں، جیسے کوئی زچہ کتیاعین سڑک کے درمیان لیٹ کر اپنے نومولودوں کو دودھ پلائے جا رہی ہو۔ہمارے ہاں کے دریا کس قدر جنگلی، نامانوس اور وحشت انگیز ہوتے ہیں۔ ان کی اس بیگانہ روی میں کس قدر رومان ہوتا ہے۔ ان کے ٹوٹے ہوئے کناروں سے اترتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کیسی کیسی دنیائیں آباد ہیں ابھی بھی ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اندر بونوں کے شہر آباد ہوں گے، لمبی لمبی دریائی گھاس کسی نیک بونے کی ڈاڑھی معلوم ہوتی ہے۔‘‘
*****
اس بار چاہنے کے باوجود میں دریا کے کنارے نہ جا سکی۔برفباری کی شدت نے موقع ہی نہ دیا۔ فرینکفرٹ میں میرا زیادہ وقت کمپیوٹر کے سامنے یا بالکونی کی کرسی پر گزرا، جہاں سے درختوں سے لٹکے برف کے سفید فانوس اندھیری رات کو روشن کرتے نظر آتے تھے۔ڈاؤن ٹاؤن کے اس پرانے قلعے کو بھی نہ دیکھا جو اب بھی قدیم خوشبو ؤں میں لپٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، نہ اس چرچ میں جا سکی جہاں میں نے جیزز کرائسٹ کے پاؤں چھوئے تھے تو محسوس ہوا تھا کہ پاؤں مجسمے کے نہیں، سچ مچ جیزز کرائسٹ کے ہیں۔یہودیو ں کی اس یادگار کو بھی نہ دیکھا جہاں انھوں نے نازی مظالم کی داستانیں زندہ کر رکھی ہیں۔ وہ زیر زمین خفیہ پناہ گاہیں جہاں بچے اور عورتیں کئی کئی دن چھپے رہے تھے اور بالآخر موت نے انھیں ڈھونڈ نکالا تھا۔پچھلی بارجرمنی کے دورے کے دوران ہم نے نازی کیمپوں اور دیوار برلن کی عبرت انگیز باقیات کو دیکھا تھا اور امریکی چیک پوسٹ کے ساتھ اس میوزیم کا بھی دورہ کیا تھا جہاں تصویروں، ویڈیو اور پرانے ساز و سامان کی نمائش کے ذریعے مشرقی یورپ اور خاص طور پر مشرقی جرمنی سے بھاگ کر مغربی جرمنی آنے والے یہودیوں کی کامیاب اور ناکام مسافتوں کی داستانوں کو زندہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کیا گیاتھا۔خدا جانے ان کہانیوں میں سچ کتنا ہے اور پراپیگنڈا کتنا؟ لیکن اگر دس فی صد بھی سچ ہو تو دل دکھا دینے کو کافی ہے۔ انسانی المیے ، خواہ وہ کسی بھی قوم، نسل یاعقیدے سے تعلق رکھتے ہوں،دل پر ایک ہی طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ مرتبہ جلاوطنی کا تجربہ سہا ہے۔اپنی مانوس زمینوں، موسموں اور معاشرتوں سے جدائی انسانی قلب و ذہن کو کیسی شاق گزرتی ہے اور کئی نسلوں تک ہجرت کا روگ خون میں کلبلاتا رہتا ہے۔یہودیوں کے خون میں یہ روگ دو مختلف رنگ اختیار کر گیا ہے۔ ایک طرف تو گہرا رنج وملال ان کے لکھنے والوں کے قلم کی نوک میں اتر آیا ہے اور دوسری طرف سرد بے رحمی اور اندھا انتقام ان کی سیاسی پالیسیوں کا محرک و رہنما بن گیا ہے۔ مجھے اس قوم کی تاریخ میں بہت دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن میں بار بار بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان انعامات کی یاددہانی ہے جو اس قوم پر خداے ذوالجلال کی طرف سے کیے گئے تھے، ان مواقع کا ذکر ہے جو بار بار اس قوم کو دیے جاتے رہے۔ آخر کوئی بات تو ایسی ہوگی اس قوم میں ، کہ خدا نے انھیں اس قدر توجہ دی۔پھرانھیں کیوں دربدر کر دیا؟ اس قدم نے جلاوطنی کا جو دکھ سہا ہے اور بار بار سہا ہے، اس کی کیا کوئی گہری وجہ بھی ہے؟
عقیدے سے ہٹ کر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ قوموں کی زندگی میں کیسے کیسے سخت مقام آتے ہیں لیکن اگر عزیمت ہو تو وہ پھر سے جی اٹھتی ہیں اورمختصر سی مدت میں خود کو دنیا بھر سے منوا لیتی ہیں۔ دوسری جنگِ عظیم کو ابھی ایک سو سال بھی پورے نہیں ہوئے لیکن یہودیوں نے نہ صرف اپنے لیے ایک وطن حاصل کرلیا بلکہ اپنی عسکری قوت، اقتصادی پالیسیوں اور سیاسی چالوں کے ذریعے عملاً دنیا بھر کی سیاست و معیشت پر قابو پا لیا ہے۔ ایسے میں اپنے دیس پاکستان کے موجودہ اندھیروں کے عقب میں بھی روشنی کی امیدسی لہراتی نظر آتی ہے۔
ہم بھی سنبھل جائیں گے۔
ہم بھی ابھر آئیں گے۔ ‘‘
جرمن قوم کی صلاحیت اور خود اعتمادی میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کا بہت سامان ہے۔مجھے جرمنوں کی ایک اور ادا بھی بہتپسند آئی وہ اپنی تہذیب و ثقافت کو محفوظ رکھنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں شہروں کی قدیم عمارتوں کی ظاہری صورت کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے پچھلی بار جب ہم مشرقی جرمنی کے خوب صورت شہر ایفرٹمیں ٹھہرے تھے تو دیکھا تھا کہ ڈاؤن ٹاؤن کی تمام عمارتیں صدیوں پرانی قدیم صورت پر قائم ہیں۔میں ایفرٹ یونی ورسٹی کے جس مہمان خانے میں ٹھہری تھی وہ بھی آٹھ سو سال پرانی عمارت میں تھا ۔یہ اس قدیم یونی ورسٹی کی عمارت تھی جسے ان دنوں پورے جرمنی کی عظیم ترین درسگاہ ہونے کا اعزاز حاصل تھا ۔ سولھویں صدی کے آغاز میں پروٹسٹنٹ ازم کا بانی مارٹن لوتھر بھی یہاں کسب علم کے لیے آیا تھا۔ یہیں ایک طوفانی رات میں اس نے راہب بننے کا تہیہ کیا اور کئی سال تک ایک خانقاہ میں ریاضت اور نفس کشی میں مصروف رہا۔وہ خانقاہ ابھی تک مارٹن لوتھر کے نام سے منسوب ہے۔ ایفرٹ مارٹن لوتھر کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل شہر تھا۔اس قدیم یونی ورسٹی کی عمارت کو اب جدید یونی ورسٹی آف ایفرٹ کے مہمان خانے کے طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے لیکن عمارت کی بیرونی وضع قدیم ہے۔لکڑی کا موٹا اوربھاری بیرونی دروازہ ایک بلند آہنگ چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا تھا۔ لکڑی کے چوڑے چوڑے نیم تاریک زینے تھے جن پر چڑھتے ہوئے روشنیاں خود بخود جل اٹھتی تھیں اور ایک عجیب پر اسرار فضا بناتی تھیں۔ عمارت کے نیچے سرنگ نما تہہ خانے تھے جو کبھی غلے اور اناج کے گودام ہو ا کرتے تھے ۔ ان کی دیواروں میں کسی غار کی دیواروں کی طرح کے ناہموار پتھر جگہ جگہ ابھرے ہوئے تھے۔ اگرچہ ان تہہ خانوں میں جدید واشنگ مشینیں نصب تھیں اور وہ لانڈری کا کام دے رہے تھے مگر ان کی قدامت کا رنگ ڈھنگ اب بھی اسی طرح قائم تھا۔ اس پر مستزاد خاموشی تھی۔ عمیق اور راز بھری خاموشی۔ اس خاموشی میں ماضی کی گونج تھی جس کی ہیبت مجھے اکثر محسوس ہوتی تھی۔ شام کے بعد زینے سے اترتے اور چڑھتے ہوئے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آہٹ آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ کئی بار میں نے بے اختیار سانس روک کر پیچھے مڑ کر دیکھاتھا۔ لیکن اس ہیبت کے باوجود اس قدیم فضا میں ایک طلسمی کشش تھی جومجھے مسلسل تین ہفتے تک محسوس ہوتی رہی۔ حتیٰ کہ دروازہ کھول کر باہرگلی میں نکلتی تو قدم ان گول گول سلیٹی پتھروں پر ڈگمگا جاتے جو سنا ہے صدیوں پرانے تھے۔ لگتا تھا تاریخ ان گلی کوچوں میں ننگے پاؤں گھوم رہی ہے۔مہمان خانے کے دروازے کے ساتھ ہی گلی ایک موڑ مڑتی تھی ۔ موڑ پر ایک قدیم گرجا کا اونچا دروازہ تھا۔ گلی سے کچھ آگے نکل جائیں تو ایک قدیم چوک تھا جس میں شام کو لوگ بید کی کرسیوں پر بیٹھ کرگپ شپ کرتے اور پیتے پلاتے تھے۔ پچھلی طرف مارٹن لوتھر سے منسوب خانقاہ تھی جہاں میں ایک سروس میں بھی شامل ہوئی تھی۔
ایفرٹ سے نکل کر ایک دن میں کرسٹینا اور امۃ المنان گوئٹے کیشہر ویمر بھی گئے تھے جہاں گوئٹے کا گھر میوزیم کی صورت میں سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ اس گھر میں اس کی تصویریں ہیں، مجسمے ہیں، سکے ہیں، اس کی محبوبہ کی یادگار یں ہیں، قیمتی اور نایاب پتھروں اور جڑی بوٹیوں کا خزانہ ہے جو اس نے دور دور سے حاصل کیے تھے۔ وہ ان پتھروں اور جڑی بوٹیوں کا اعلیٰ پارکھ تھا۔ وہ کمرہ ہے جہاں اس نے آخری سانس لیے تھے اور کہا تھا: روشنی !! اور روشنی!!!
واپسی پر ہم نے بس کی کھڑکی سے کئی چھوٹے چھوٹے قصبے دیکھے ۔ ان قصبوں میں اب صرف بوڑھے رہتے ہیں۔ جوان لوگ پڑھنے یا نوکری کرنے شہر جا چکے ہیں۔ کئی بڑی بڑی حویلیاں خالی پڑی تھیں اور ان پربرائے فروخت کے بورڈ لگے تھے۔ کئی ایک پر تو قیمت بھی لکھی تھی، ایک یورو، صفر یورو۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ قیمت واقعی اتنی کم ہے یا مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ کرسٹینا نے بتایا کہ ان قدیم مکانوں کی ظاہری اور تاریخی وضع قطع بدلنے کی اجازت نہیں ہے ا س لیے ان کی دیکھ ریکھ پر بہت خرچ آتا ہے۔ مالک مکان اس خرچ سے بچنے کے لیے انھیں مفت دینے کو تیار ہیں مگر انھیں خریدنے والا کوئی نہیں۔ مجھے یاد آیا کہ ایفرٹ میں بھی ایسے کئی مکان ہیں جو اندر سے بالکل جدید طرز زندگی کے مطابق ہیں مگر بیرونی ڈھانچا قدیم ہے۔ یہ لوگ اپنے قدیم فن تعمیر کے شاہ کاروں کو زیادہ سے زیادہ دیر تک قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے تہذیبی ورثے سے یہ محبت ان کے قومی تشخص کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یوں فلسفیانہ طور پر دیکھا جائے تو یہ محض ایک خود فریبی ہے۔ انسان اس کرہ ارض میں کتنے قرنوں سے آباد ہے۔ سنا ہے اہرامِ مصر پچیس ہزار سال قبل مسیح میں تعمیر ہوئے تھے۔ کتنی ہی تہذیبیں اس سطح زمین پر پھلی پھولیں اور فنا کے گھاٹ اتر گئیں۔ ہر نام بالآخر فراموشی کے دریا میں بہہ جاتا ہے لیکن پھر بھی انسان اپنے ماضی سے رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے اور اپنی شناخت کے لیے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے۔
جرمنوں کے لیے اس شناخت کا ایک پہلو ہٹلر بھی ہے۔ مجھے یاد ہے ایفرٹ یونی ورسٹی کی ایک نوجوان طالبہ کیٹرین ایک روز میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور کہنے لگی کہ ہم جرمن بہت شرمندہ ہیں۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم ہٹلر کے ہم قوم ہیں۔ میں حیرت سے ا س کا منہ دیکھتی رہ گئی۔
مگر اس میں تمھارا کیا قصور ہے؟ میں نے پوچھا تھا۔
’’میرا بھی قصور ہے۔ ہم سب کا قصور ہے ۔۔۔۔ ‘‘ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔
میں سوچتی رہ گئی کہ یہ پروپیگنڈے کی طاقت ہے یا کچھ اور۔ کسی قوم کو اس کے ماضی پر اس قدر شرمسار کر دینا۔ کیا حال اور مستقبل کے سب لوگوں کو ماضی کا خراج دینا پڑتا ہے؟ ماضی جو ہمارا دوسرا پاؤں ہے جسے اٹھا کر ہم کھڑے نہیں رہ سکتے۔ ماضی جو ہماری تقدیر ہے۔ ماضی جو ہمارا جبر ہے۔ ماضی سے کوئی کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟