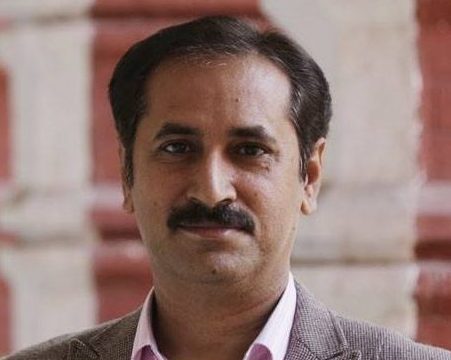
(ناصر عباس نیر)
۵؍جون ۲۰۱۱ء
ایک دوسرے ملک، جس کا کلچر بھی ’دوسرا‘ ہو،اس میں رہنے سے آدمی کئی باتیں سیکھتا ہے۔ نئی نئی معلومات، نئے طریق کار،نئے نظام،نئے لوگوں سے دوستی کے علاوہ جو اہم بات آدمی سیکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا سے مختلف دنیا میں اور اس کے ساتھ رہنا سیکھتا ہے۔ یہ بلاشبہ اس دنیا سے مختلف ہے، جس سے میں ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھا ہوں (مگر شاید ہی کوئی پل ہو جب وہ میرے ساتھ نہ ہو)۔ میں اس کی سب باتوں سے اتفاق کرسکتاہوں، نہ ان کی ہر بات کو اعلیٰ درجے کا حامل سمجھتا ہوں،نہ ہراس بات کی تقلید کے حق میں ہوں،جو مجھے ایک وقت میں بہت اچھی لگتی ہے۔میں اپنے دل ودماغ کو کھلا رکھنے کی مقدور بھر کوشش کرتا ہوں تاکہ ان کی اچھی باتوں کی تحسین کرسکوں،اور اس میں اپنے ثقافتی ،مذہبی، اخلاقی معیارات اور تعصبات کو آڑے نہ آنے دوں۔اگرچہ دنیا کا سب سے مشکل کام یہ ہے کہ اپنے ثقافتی معیارات وتعصبات کے جبر کو اس وقت معطل کرنا ہے ،جب وہ دوسروں کے معیارات سے مختلف اور متصادم ہوں۔یہ ایک نازک ترین لمحہ ہوتا ہے ،قریب قریب بحرانی لمحہ جب آپ ان چیزوں سے دوسروں کو لذت کشید کرتے دیکھتے ہیں،جنھیں آپ یکسر ممنوع تصور کرتے ہیں۔آپ خود کو مجبور پاتے ہیں کہ فیصلہ کریں کہ کون درست ہے؟ آپ کے سامنے میز پر ایک شخص اس پارہ گوشت کو شوق اور رغبت سے کھارہا ہے، جس کا نام لیتے ہی آپ کو ابکائی محسوس ہوتو اس لمحے آپ بحرانی حالت میں ہوتے ہیں۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اس لمحے فیصلہ نہیں کرنا، دوسروں کوتسلیم کرنا ہے۔ان کے شوق اور رغبت میں شریک نہ ہونے کے باوجود ،ان کے انتخاب کوان کا حق سمجھنا ہے۔یوں بھی میزبانوں پر تنقید کا حق مہمان کو بالکل نہیں۔
میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ اس طرح کے بحرانی لمحوں میں ہم عموماً تین طرح کے رویے ظاہر کرتے ہیں۔ اخلاقی، ثقافتی اور جمالیاتی۔ اخلاقی رویہ دوسروں کا محاسبہ کرتا ہے ،اور محاسبے کے لیے ہم حرام حلال، غلط صحیح کے اپنے تصورات کو بنیاد بناتے ہیں۔ ثقافتی رویہ، دوسروں کے ساتھ ان کے عمل میں شریک ہونے سے عبارت ہے، جب کہ جمالیاتی رویے میں آپ دوسروں کے عمل سے فاصلے پر ہوتے ہیں، مگران کے عمل کے حسن کی ستائش کرتے ہیں،اور ان کے عمل کی بد صورتی پر خاموش رہتے ہیں۔میں یہاں بعض پاکستانیوں سے مل چکا ہوں، جو ہر وقت اخلاقی فیصلے صادر کررہے ہوتے ہیں،انھیں کافر، عیش پسند و عریاں پسند جانے کیا کیا نہیں کہتے،لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اگر ایسا ہی ہے تو اپنے ملک واپس چلے جائیں تو ناراض ہوجاتے ہیں۔ان کا اصل مسئلہ ،ان کی اولادیں ہیں۔وہ خود یہاں کی آزادی سے فیض یاب رہنا چاہتے ہیں،مگر اولاد ،خصوصاً لڑکیوں کے باب میں چاہتے ہیں کہ انھیں اس آزادی کی ہوا تک نہ لگے۔وہ بسترو پر بیٹھے ایک حسین دوشیزہ کے ہاتھ سے لے کر بئیر ، شراب ،کافی،جوس پی لیں گے، ایک نظراس کی ننگی پنڈلیوں،اور کھلے گریبان سے جھانکتی سڈول چھاتیوں پربھی ڈال لیں گے، لیکن یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ کام ان کی بیٹی کرے ،یا سکرٹ پہن کر باہر نکلے،یا اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو۔وہ مسلسل ایک عجیب مخمصے میں گرفتار رہتے ہیں۔وہ خود یہاں رہنا چاہتے ہیں،مگر اولاد کے ذہن میں اس ملک کے کافر، لامذہب، فحش ،گناہ گار ہونے کا احساس پیدا کرکے، انھیں واپس پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں۔
میں دیکھتا ہوں کہ ہر ویک اینڈ پر نوجوانوں کے پرے کے پرے کیمپس کے اندر کسی جگہ جمع ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جا م پر جام لنڈھاتے ہیں۔ یہ محض پکنک نہیں نہ فقط موج مستی ہے، یہ اس ’’خاندانی نظام‘‘ کا ریپلیکا ہے، جسے یہاں کے اکثر نوجوان(سب نہیں،مثلاًڈاکٹر کرسٹینا کی بیٹی نے گھر نہیں چھوڑا) اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچتے ہی خیرباد کہہ دیتے ہیں۔ وہ اپنے قانونی حق کو استعمال کرتے ہوئے خاندانی نظام کی اس مثلث کو توڑتے ہیں، جس کے دو کونے ان کے والدین اور تیسرا کونا یہ خود ہوتے ہیں اور ویک اینڈ یا کسی دوسری تعطیل کے موقع پر یہ اس مثلث کی نقل اتارتے ہیں۔ نقل ا س لیے کہا ہے کہ اس میں وہ دو کونے موجود ہی نہیں ہوتے، جن کے بغیر خاندانی نظام کا تصور بھی محال ہے۔ جب یہ لوگ اپنے درمیان آگ کا الاؤ روشن کرکے ناچتے گاتے ہیں تو اپنے قدیمی آباؤ اجداد کی ابتدائی قبائلی زندگی کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں، مگر یہ نئے عبد کے ڈیموکریٹ قبائل ہیں جن میں کوئی سربراہ نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں__ میں خاندانی نظام کے اس ریپلیکا کو قبول نہیں کر سکتا، مگر اسے مسترد بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کم از کم اس یقین کا نہایتقوی اظہار ہے کہ فرد کی غیرمحدود آزادی کے باوجود خاندانی نظام ختم نہیں ہو سکتا__ اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ جوں ہی دھوپ نکلتی ہے، خواتین کے جسم پر محض دودھجیاں سج جاتی ہیں۔ ہر دوسرے قدم پر نوجوان (اور بزرگ بھی) جوڑے سرعام بوس و کنار کرنے لگتے ہیں۔ کوئی ان کی طرف توجہ دیتا ہے نہ یہ کسی کی پروا کرتے ہیں۔ اس آزادی کو ’’رشک بھری نگاہوں‘‘ سے دیکھنے کے باوجود میں اس کی تقلید کرنیپر خود کو آمادہ نہیں پاتا، مگر میں اسے ایک لمحہ کے لیے غلط یا گم راہ کن قرار نہیں دے سکتا۔ جس بات کو کوئی سماج اجتماعی طور پر قبول کر لیتا ہے، اس پر حرف زنی کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ میرے نزدیک جس سماج میں جسم کو ڈھانپے رکھنے کو اخلاقی قدر قرار دیا جاتا ہے، اس پر بھی کسی کو حرف گیری کا حق نہیں۔ ہر ’مختلف‘ کو ’غلط‘ اور ’گم راہ کن‘ قرار دینے کا رویہ سخت تباہ کن ہے۔ اس بات کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اسی بات کو اعلیٰ ترین سچائی کا درجہ دیتے اور اس کے نفاذ کی خواہش رکھتے ہیں، جو آپ کی دنیا میں اور کلچر میں رائج ہے۔ یہ شدید ترین نرگسیت اور ایک جہاں گیری کی لاشعوری خواہش ہے، جو موجودہ دنیا میں فقط بتا ہی لاتی ہے__
۷؍جون ۲۰۱۱ء
آج ویزے میں توسیع کے لیے وقت مقررہ پر(۱۲ بجے دن) پرانے شہر میں واقع یونیورسٹی کے ایک دفتر میں گیا۔ میرے ساتھ سٹیفا نولیلی تھا۔سٹیفانو اطالوی نوجوان ہے اور بے حد ملنسار اور مخلص۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جو شخصہفتے میں ایک دن (ہر منگل کو) اس یونیورسٹیکے غیرملکی اساتذہ اور محققین کے ویزوں میں توسیع یا اس طرح کے دیگر مسائل کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کی کچھ خبر نہیں، نہ اس نے کوئی اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا تو پاکستان میں ہوتا ہے،۔ایک خاتون نے برجستہ کہا کہ جرمنی میں بھی ہوتا ہے۔ میں نے جواب آں غزل کے طور پر کہا کم از کم اس معاملے میں ہم ایک ہیں۔ خیر! وہاں دیگر لوگوں نے ہم سے ہمدردی کی، فارم دیا اور جمعرات کو نیون ہائمر میں ایک دفتر میں آنے کے لیے کہا__ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ وہیں اولڈ مینزا میں کھانا کھایا۔ سٹیفا نو نے اصرار کے ساتھ مجھے اپنا مہمان بنایا۔ اس مینزا کی عمارت قدیم ہے۔ سرخ رنگ کے پتھر سے بنا یہ پرانا مینزا مجھے بہت اچھا لگا۔ ایک مرتبہ پہلے یہاں کافی پی تھی، مگر آج کھانے کا انوکھا لطف ملا۔ فقط اس لیے نہیں کہ وہاں کھانے کی اقسام زیادہ تھیں اور نسبتاً لذیذ بھی تھا، بل کہ اس لیے بھی کہ گھنے درختوں کے سائے میں لگی میز کرسیوں پہ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آج موسم بھی گرم نہیں تھا۔ قدیمی عمارت، فطرت اور گھر کے صحن کی طرح مگر اس سے کہیں کشادہ ماحول میں، جہاں اور بھی کئی نظر فریب نظارے تھے۔مچھلی ، سلاد کی چند قسموں اور مٹھی بھر اُبلے چاولوں کو کھانا ایک یادگار تجربہ ثابت ہوا۔
آج منگل تھا،اور اس روز ہندی اردو کی بات چیت ہوتی ہے۔دیر سے پہنچا،یعنی کوئی پونے تین بجے۔کلاس میں کوئی خاص بات نہیں۔وہی جملے، وہی خبریں،اور ہلکی پھلکی بات چیت۔
۹؍جون ۲۰۱۱ء
ڈاکٹر کرسٹینا کے ارشاد کی تعمیل میں مختلف سیمسٹرز کے یورپی(زیادہ تر جرمن) طالب علموں کو ابتدائی جدید اردو تنقید پر لیکچر دیا۔ پہلی مرتبہ ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر انگریزی میں دیا۔ میں نے ڈاکٹر کرسٹینا سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں لیکچر میں وہی باتیں کہوں گا جو میں درست سمجھتا ہوں۔ یہاں کے طالب علم ڈاکٹر صادق کی ہسٹری آف اردو لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں اردو ادب پر انگریزی اثرات سے شروع ہونے والے عہد کو ’آزادی اور نشاۃ ثانیہ کے عہد‘ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ بات سرے سے نظر انداز کر دی گئی ہے کہ انگریزی ادب کے اثرات، ہندوستانیوں کو یورپی طرز پر مہذب بنانے کے بڑیثقافتی منصوبے کا حصہ تھے۔ ڈاکٹر صادق مغربی اثرات کی مدح میں اسی مبالغے سے کام لیتے ہیں، جسے برصغیر کے انگیز حکام اردو شاعری میں فرض کرتے تھے اور سخت ترین تنقید کا نشانہ بناتے تھے__ انھوں نے کہا کہ آپ وہی پڑھائیے جو آپ کو درست لگتا ہے۔ بہرکیف میں نے لیکچر دیا اور پوری توجہ اس بات پر تھی کہ اواخر انیسویں صدی کے چار اردو نقاد اہم تھے: آزاد، حالی، اثر اور شبلی۔ چاروں نقاد اور شاعر تھے۔ چاروں کلاسیکی مشرقی علوم کی روایت میں پیرے ہوئے تھے۔ چاروں مختلف سطحوں پر مغربی ادیبات سے متاثر تھے۔ اس عہد میں دو تحریکیں مغربی اثرات کے فروغ میں پیش پیش تھیں۔ انجمنِ پنجاب اور علی گڑھ۔ آزاد انجمن پنجاب سے، حالی انجمن اور علی گڑھ دونوں سے، شبلی علی گڑھ سے وابستہ تھے۔ واحد غیر وابستہ نقاد امداد امام اثر تھے اور ان کی غیروابستگی ہی انھیں اس عہد کا ممتاز نقاد بناتی ہے۔ آزاد، حالی اور شبلی کے انگریزی ادب کے براہِ راست استفادے کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ حالی اور شبلی دونوں نے، دوسرے لوگوں کے تراجم پر انحصار کیا، مگر اثر نے براہِ راست انگریزی تنقید کا مطالعہ کیا، اگرچہ جتنا مطالعہ انھوں نے مغربی کلاسیکی ادبیات کا کہا، اتنا انگریزی تنقید کا نہیں کیا۔ میرا یہ بھی مؤقف تھا کہ انجمن پنجاب ، سرکاری سرپرستی،اور سرکاری طور پر طے کردہ مقاصد کے تحت چلنے والی تنظیم تھی،جب کہ علی گڑھ تحریک مقامی لوگوں کی تھی، مگر حکومتی آئیڈیالوجی کی حامی تھی۔ شبلی نے سرسید سے تعلیم ، مذہب اورمغرب کے تہذیبی اثرات کے حوالے اختلاف کیا، مگر ان کی تنقید کا وہ حصہ جومغربی تنقید سے متاثر ہے، سرسید کے مغرب سے متعلق عمومی نقطہ نظر سے مکمل ہم آہنگ ہے__ خیال تھا کہ لیکچر کے خاتمے پر طالب علم سوال کریں گے مگر فقط دو ایک سوال پوچھے گئے۔ مجھے حیرت ہوئی__ میں نے اس خاموشی، کو ڈاکٹر کرسٹینا سے کل ہی کافی پر ہونے والی اس گفتگو سے جوڑ کر دیکھا ہے جو ۱۹۶۸ء کی طلبا کی بغاوت سے متعلق تھی۔ یہ بغاوت ہائیڈل برگ یونیورسٹی میں، پورے جرمنی میں، فرانس میں اور کچھ دوسرے ملکوں میں بہ یک وقت شروع ہوئی تھی۔پوسٹ ماڈرن ازم کے آغاز کو اس بغاوت سے جوڑ کر دیکھا جاتاہے۔ جرمنی میں یہ بغاوت فاشزم کے خلاف تھی۔ طالب علموں نے یونیورسٹی کے معاملات میں اپنی نمائندگی کا مطالبہ کیا تھا؛ اپنی تقدیر سے متعلق فیصلوں کو انتظامیہ کا استحقاق سمجھنے کے خلاف آواز اٹھائی تھی، مگر اب انھی جامعات کے طالب علم سوال تک نہیں اٹھاتے۔ کیا اس لیے کہ اب فاشزم موجود نہیں؟کیا بڑے سوال اٹھانے کے ایک عظیم شر کاموجود ہونا ناگزیر ہے ؟کیا انسانی ذہن بڑے سوال قائم کرنے کے لیے ،انتہائی برے، مبارزت طلب حالات کا مرہون ہے؟اگرا یسا ہے توجسے ہم بڑ ا سوال کہتے ہیں، وہ ایک حقیقی مادی مسئلے کو سمجھنے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔کیا واقعی؟
اب اگر کبھی آواز اٹھائی جاتی ہے تو ان سیمینار کے کمروں کی کشادگی کے لیے، جہاں داخلہ لینے والے سارے طالب علم کرسیوں پر نہیں بیٹھ سکتے۔ محض بیٹھنے کی جگہ حاصل کرنے کے لیے آواز؟ظاہر ہے ،اس مسئلے کے لیے کتنی اونچی ،اور دبنگ آوازدرکار ہوگی؟ کیا اب بڑے فکری مسائل کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں یا یہ مسائل سرے سے موجود ہی نہیں؛ دائیں بائیں کا ٹنٹا ختم ہونے کی جو فضایہاں موجود ہے، اس کا مظاہرہ میں نے گذشتہ برس خود اپنی یونیورسٹی کے اکیڈمک ایسوسی ایشن کے انتخابات میں بھی دیکھا تھا، جس میں جماعت کے پروفیسروں اور ترقی پسندوں نے مل کر الیکشن لڑا تھا۔دونوں میں اتفاق کا سادہ سا مطلب ہے کہ نظریہ وزریہ کچھ نہیں،مفاد اہم ہے۔کیا ہمیشہ سے مفاد ہی اہم تھا، جس پر نظریے کا غلاف چڑھا تھا؟یا یہ سب نظریوں کی ناکامی کا ایک مایوسانہ مگر خود غرضانہ ردّعمل ہے؟کیا اس ساری صورتِ حال کا تعلق سرد جنگ کے خاتمے سے ہے؟ان سب سوالوں پر غور کی ضرورت ہے، لیکن ا س سے بھی زیادہ غور طلب معاملہ یہ ہے کہ آخر کیوں پاکستان کی جامعات میں دائیں بائیں کی شناختوں کے مٹنے پر نہ کوئی مرثیہ ہے ، نہ مقالہ؟ جامعات سے باہر بھی صورت حال کچھ مختلف نہیں۔
کوئی بڑی وجہ ضرور موجود ہے کہ اب بڑے سوال نہیں اٹھائے جا رہے__ میں ساؤتھ ایشیا انسٹی ٹیوٹ کے گیسٹ اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں اور اکثر شام کی سیر کے بعد جس راستے واپس آتا ہوں، وہاں کچھ طالب علموں نے ’’کیمپ ان کیمپس‘‘ کے نام سے کچھ خیمے لگا رکھے ہیں۔ یہ احتجاجی کیمپ ہے۔ جی ہاں! ایک انوکھا احتجاج۔ کوئی نعرہ نہیں کوئی راستہ بندنہیں، کہیں شور سے اپنی موجودگی اور اپنے مؤقف کا اظہار نہیں۔ شام کو آگ جلا لیتے ہیں، وہیں کھانا وانا تیار کر تیہیں۔گا بجا لیتے ہیں، پی پلا لیتے ہیں، چوماچوٹی تو خیر کسی وقت بھی کر لیتے ہیں۔ اس علامتی احتجاج کا یقیناًکوئی مفہوم یورپی تناظر میں ہوگا، مگر صاف لگتا ہے کہ جو آگ کا الاؤ وہ شام کو روشن کرتے ہیں اور قدیم قبائلی طرزِ حیات کا محدود احیا کرتے ہیں، وہ ان کے سینوں میں روشن نہیں، ورنہ یہ سرسبز گھنے درختوں سے گھریمیدان میں کیمپ نہ لگاتے۔ مقتدرہ کے سینے پر مونگ دلنے کے لیے اس کے مرکز اقتدار کے سامنے کیمپ لگاتے۔ میں سوچتا ہوں، اب شاید یہاں بڑے سماجی اخلاقی، معاشی مسائل و سوالات اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتے۔ جہاں صحت، تعلیم، آمد و رفت، صفائی، خوراک، مکان سب کو میسر ہو۔ ریاست نے بلاامتیاز سب شہریوں کو زندگی کی بنیادی ضرورتوں کی فراہمی کو یقینی بنا دیا ہو، جہاں فرد کی آزادی کی ضمانت ہو، آپ گے ،لزبین کے طور پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، یاشادی کے بغیر رہنا چاہتے ہیں، سنگل پیرنٹ کے طور پر یا اکٹھے__ آپ کو اختیار ہو۔ یعنی آپ کی طبعی، جذباتی اور جبلی ضرورتوں کی تسکین میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہاں بڑا سوال فقط باطنی، روحانی نوعیت کا ہوتا ہے، جس کی زد پر کوئی کوئی آتا ہے اور اس کے لیے احتجاج نہیں، تلاش کی جاتی ہے__ ممکن ہے یہ تجزیہ درست نہ ہو، مگر یہاں کے لوگوں کے رویوں سے ظاہر یہی ہوتا ہے__ حقیقت یہ ہے کہ احتجاج و بغاوت،اور بڑے سوالات اٹھانے کے لیے سب سے موزوں ممالک ہمارے ہیں، پاکستان اوربھارت۔ عرب ملکوں میں تو خیر ٓاج کل بغاوتیں عروج پر ہیں۔دیکھیے ان کا انجام کیا ہوتاہے؟
آج ویزے میں توسیع کی درخواست جمع کروا دی ہے۔ آج ویزے سے متعلقہ خاتون وقت مقررہ پر اپنے دفتر موجود تھی اور میری منتظر!




