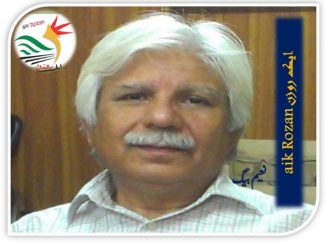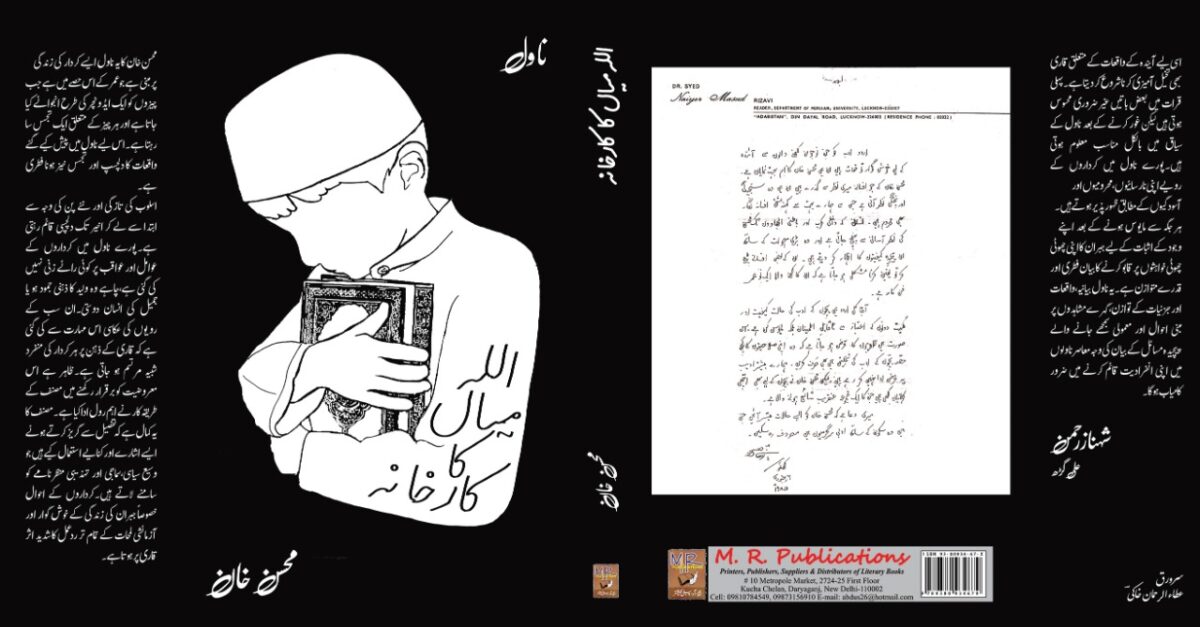
کارخانۂ قدرت اور انسانی جبلت کا تضادیہ اور سوالیہ
از، پروفیسر علی احمد فاطمی
فکشن کے ممتاز ناقد وارث علوی نے بہ آسانی کہہ تو دیا: ’’ناول بِن جینا بھی کوئی جینا ہے۔‘‘
ناول صرف ایک کتاب نہیں ہوتا صرف ایک قصہ نہیں ہوتا، بَل کہ کتابِ زندگی ہوتا ہے، زندگی کا فلسفہ ہوتا ہے۔ یہ صرف زندگی کا بالترتیب واقعہ نہیں ہوتا، بَل کہ بے اعلان رزمیہ ہوتا ہے۔ اس میں زندگی کا صرف کیف و کم نہیں ہوتا، بَل کہ سرد و گرم اور پیچ و خم بھی ہوتا ہے۔
یہ سیدھی لکیر سے زیادہ آڑی ترچھی لکیروں اور زندگی کے کراس (cross) سے جنم لیتا ہے۔ اس میں جتنے تضادات و تصادمات ہوں گے جتنے قولِ محال (paradoxes) ہوں گے، جتنے اُلجھاوے ہوں گے، ناول کی کیفیت، کمیت اور تخلیقیت میں اتنی ہی جان ہو گی؛ اور یہ قولِ محال، محال دَر محال ہے اس لیے آسان نہیں۔
غالباً اسی لیے مغربی دانش وروں نے ناول نگاروں کا بے حد عزت و احترام سے ذکر کیا ہے۔ لارنس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک سائنس داں، فلسفی، حکیم سے زیادہ کارگر مؤثر و معتبر ناول نگار ہوتا ہے۔ خود اپنے بارے میں ایک جگہ لکھا:
’’میں زندہ انسان ہوں اور جب تک میرے بس میں ہے میرا ارادہ زندہ انسان رہنے کا ہے اسی لیے میں ایک ناول نگار ہوں اور چُوں کہ میں ایک ناول نگار ہوں اس لیے اپنے آپ کو کسی سَنّت، کسی فلسفی، کسی شاعر سے بر تر سمجھتا ہوں۔‘‘
یہ وقار و اعتبار اس لیے ہے کہ ناول ادب کی سب بھاری بھرکَم صنف ہے، پھیلی ہوئی صنف ہے، جیسے کی زندگی کی وسعت اور پیچیدہ حقیقت۔
اسی لیے ورجینا وُلف نے کہا تھا کہ ناول شتر مرغ کی طرح ہوتا ہے جو ہر سخت اور کھردری شے کو ہضم کر لیتا ہے۔
ای ایم فورسٹر نے بھی کہا تھا:
’’انسانی زندگی کے سخت اور نرم، کھلے اور پوشیدہ پہلووں کو ظاہر کرنے کی جو قوت ناول میں پائی جاتی ہے وہی اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اور یہی اسے دیگر فنون سے متماز بھی کرتی ہے۔‘‘
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناول کے تعلق سے یہ سب تعریفیں پرانی ہو گئی ہیں اور آج کا ناول ان تعریفوں سے آگے نکل گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سچ ہو؛ زندگی خواہ کتنی ہی بدل جائے، ترقی کر جائے لیکن کچھ بنیادی باتیں اور قدریں بَہ ہر حال قائم رہتی ہیں۔
سماج اور معاشرہ کا مرکز، کَل بھی انسان تھا اور آج بھی انسان ہی ہے۔ ناول عام طور پر انسانی زندگی کے پیچ و خم کو پیش کرتا ہے، اگر چِہ نئی تعریف میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بَہ قول مِیلان کنڈیرا:
’’انسانی تاریخ اور ناول کی تاریخ دو مختلف تاریخیں ہیں۔ ایک دوسرے سے قربت کے با وجود ایک دوسرے سے دور اور اپنی جگہ قائم بِالذات۔‘‘
ایسا اس لیے ہے کہ سماجی حقیقت اور تخلیقی حقیقت میں بَہ ہر حال فرق ہوتا ہے۔ سماجی حقیقت کھردری حقیقتوں (crude reality)کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور تخلیقی حقیقت میں کچھ آرزو، کچھ آدرش اور کچھ خواب شاملِ تخلیق رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تخلیق صرف زمانے کی تصویر یا تقدیر نہیں ہوتی، بَل کہ تخلیق کار کی اپنی تعبیر بھی ہوتی ہے؛ تعبیرِ نو اور تنقید نو بھی۔
ان خیالات سے کوئی اتفاق کرسکتا ہے تو بَہ صد شوق اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ بڑا ناول صرف ناول نہیں ہوتا، بَل کہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔
ٹیگور نے اپنے ناولوں کے بارے میں ایک جگہ کہا تھا کہ اگر میرے ناولوں کو صرف ناول سمجھا گیا تو یہ کُفر ہو گا۔ یہ افسانہ ناول کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ بڑا فن کار اپنی دنیا خود خلق کرتا ہے جیسے خدا نے یہ دنیا خلق کی جس کو سمجھنے کے لیے تفکیر و تخلیق کے پیمانے چھوٹے پڑ جاتے ہیں؛ کبھی کبھی بڑے ناول کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ تنقید و تحقیق کے پیمانے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ کیا کیا جائے کہ یہی ادب کا کارخانہ ہے اور یہی اللہ میاں کا کارخانہ۔
اللہ میاں کا کارخانہ، محسن خاں کے نئے ناول کا عنوان بھی ہے۔
عنوان سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا قدم ہے۔ عموماً ناول نگار کارخانۂِ خدا کے کسی کفر نما واقعہ کو منتخب کر کے اشاراتی و تخلیقی عمل سے گذر جاتا ہے، لیکن پورے کارخانے پر نظر رکھنا اور عنوان میں اللہ سے منسوب کر کے سوال اٹھانا بھی اپنے آپ میں جرأت و جسارت بھرا قدم ہے۔ حالاں کہ اس میں نہ اللہ کا معاملہ ہے نہ اس کے کارخانے کا۔
یہ مسئلہ تو اس کَل پرزے کا ہے جس سے یہ کارخانہ چلتا چلاتا ہے یعنی حضرتِ انسان کا؛ اس لیے کہ وہی اس کائنات کا مرکز و مِحوَر ہے وہی جنگ اور امن (War and Peace) ہے وہی جرم و سزا (Crime and Punishment) وہی قانون ساز ہے اور وہی قانون شکن بھی۔ اسی کی پیشانی پر نشانِ سجدہ ہے اور اسی کے ماتھے پر شکن در شکن بھی۔ جہاں شکن نہیں ہے وہاں وہ آگ کے دریا سے گذر جاتا ہے جہاں تہذیب و تعبیر کی گنگا بہتی رہتی ہے۔
کئی دھائیاں قبل محسن خاں نے اپنے چند افسانوں (بالخصوص زھرہ) سے اپنی پہچان کی توانا بنیادیں رکھی تھیں۔ پریم چند نے کہیں لکھا تھا کہ آسان کہانی لکھنا اسی طرح مشکل ہے جیسے مشکل کہانی لکھنا آسان۔ اسی لیے اکثر جدید افسانہ نگار پیچیدگیوں کو سہولت و کیفیت کے بَہ جائے مزید الجھنوں اور پیچیدگیوں کے ساتھ پیش کرنے کو ہی جدید فن قرار دیتے رہے ہیں۔ اسی لیے وہ کافکا، کامیُو کنڈیرا وغیرہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ ٹالسٹائی، چیخوف دستووسکی وغیرہ کا کم؛ پریم چند کا تو بالکل ہی کم۔
سچے تخلیقی عمل میں عدم تکمیلیت اور عدم تحفظ کے عناصر زیادہ کارِ فرما ہوتے ہیں۔ ایک بے نام احساس و اضطراب جو آگے چل کر کبھی کبھی احتجاج کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اضطراب کے عموماً دو ہی راستے ہوتے ہیں: اوّل یہ کہ یہ دنیا فانی ہے اور جب سب فنا ہو جائے گا تو عمل و عقل چِہ معنی دارَد بَہ قولِ غالب ؎
جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود
پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟
جب یہی سوال ناول میں اترتا ہے تو موت کی کتاب لکھوا جاتا ہے جو زندگی سے بھر پُور ناول نہیں بن پاتا؛ لیکن جب وہی غالب یہ کہتے ہیں ؎
ہوَس کو ہیں نشاطِ کار کیا کیا
نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا
تو شاعرِ محشر خیال دنیا کو بازیچۂِ اطفال سمجھنے لگتا ہے اور ناول نگار اس کارخانہ پر سوالیہ نشان لگانے لگتا ہے۔
محسن خاں ملیح آباد کے پٹھان ہیں۔ جوش کی طرح جوشیلے، سجیلے اور کہیں کہیں نکیلے بھی۔ وہ فکشن ضرور لکھ رہے ہیں لیکن ان کا سنجیدہ رویہ و نظریہ اس میں بھی نکیلا پن پیدا کر کے زندگی کی بے رحم حقیقتوں کو فلسفہ بناتا چل رہا ہے اور لارنس نے بھی کہا تھا کہ فکشن جب تک فلسفہ نہ بن جائے فکشن کہلائے جانے کا حق دار نہیں ہوتا۔
چُوں کہ کارخانہ اللہ میاں کا ہے اس لیے ناول کا آغاز فجر کے وقت وضو، نماز اور سپارہ سے ہوتا ہے۔
بچے جبران کا کردار ناول کا مرکزی کردار ہے جو خواب میں پتنگ اڑا رہا ہے لیکن حقیقت میں اسے کڑکڑاتے جاڑے میں گرم لحاف چھوڑ کر نماز ادا کرنی پڑ رہی ہے، یعنی خواب میں وہ بلندی پر ہے اور حقیقت میں بندگی پر اور یہ بھی خوف کہ آج جمعہ ہے اسے نہانا بھی پڑے گا، لیکن آج چھٹی کی راحت بھی ہے تو راحت و اذیت کے متضاد احساس سے ناول کا آغاز ہوتا ہے۔
یہ متضاد احساس ہی اَزلی مقدّر ہے اور مکدّر بھی۔ ازل سے ابد تک کا سفرِ حیات ناول میں رومان بن کر تخلیقی وجدانی کا حصہ بنتا ہے۔ پریم چند نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ناول اپدیشوں سے نہیں، نصیحت سے نہیں، بَل کہ جذبات کو متحرک کر کے دل کے نازک ستاروں پر چوٹ لگا کر لکھا جاتا ہے۔
جبران پر ایک ہلکی سی چوٹ سے ناول کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر چوٹ در چوٹ کا سلسلہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ معصوم بچے کا یہ احساس:
’’جاڑوں میں نہاتے وقت میں سوچا کرتا تھا اللہ میاں کو تو یہ بات معلوم ہی ہو گی کہ جاڑوں کے دنوں میں بچوں کو نہاتے وقت کتنی سردی لگتی ہے تو پھر انھوں نے جمعہ کا دن سردیوں میں کیوں رکھا۔ وہ تو اسے گرمیوں میں بھی رکھ سکتے تھے۔ اگر یہ نہیں کرنا تھا تو جمعہ کے دن گرمی ہی کر دیا کریں۔‘‘
جاڑے میں بچے کی نہانے سے متعلق یہ معصوم لرزیدہ سوچ در اصل اشاریہ ہے اس پیدا ہونے والی آزاریہ سوچ کی جو آگے بڑھ کر ناول کا مرکزی خیال بنتی ہے جس کے سلسلے مذہبی اور سماجی نظام سے جڑے ہوئے ہیں؛ لیکن بچے کی معصوم نفسیات کا آغاز پُر کشش انداز میں ہوتا ہے اور ناول قاری کو اپنی گرفت میں لیتا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے جس پر نئے ناول نگار کم توجہ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ناول ایک تخلیقی فن پارہ ہے، سماجی دستاویز نہیں۔ ایک اشاریہ بھی دیکھیے جو کس قدر شفاف اُسلُوب میں قدرت کے نظام اور بچوں کے مقام کو ظاہر کرتا ہے:
’’جاڑوں کے دنوں میں ذرا سی دیر میں صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو جاتی تھی اور ہم نہ زیادہ دیر تک کھیل کود پاتے تھے نہ پتنگ اڑا پاتے تھے۔ پانچ وقت کی نمازوں میں وقت اور چلا جاتا تھا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ یہ دن ذرا اور لمبے ہو جائیں تو کتنا اچھا ہوتا مگر ایسا کہاں ہو سکتا تھا۔ اللہ میاں نے دن اور راتیں جیسے بنائے ہیں ویسے ہی رہیں گے انھیں گھٹایا جا سکتا ہے اور نہ بڑھایا جا سکتا ہے…‘‘
جاڑے میں نہانا، مرغی کو باہر نکالنا، دانا ڈالنا محض ایک اتفاقی اظہاریہ نہیں، بَل کہ بچوں کی فطرت و جبلت کے تعلق سے وہ بلیغ اشارے ہیں جو خارجی نظام کے جبر کے تحت انسان کے داخلی محرکات و جذبات پر قدغن لگاتے ہیں اور انسان اپنی فطری آزادی کے بَہ جائے صبح و شام اور گردشِ ایام کے بھنور میں پھنسا بچپن سے ہی غیر فطری عمل سے دو چار رہتا ہے جہاں پتنگ اڑانے سے زیادہ نہانے میں بھی ثواب نظر آتا ہے کہ جب بہن نصرت کہتی ہے:
’’بھیا مجھے تو نہانے میں بڑا ڈر لگتا ہے،‘‘ تو ماں نے کہا، ’’اللہ تم لوگوں کو ان عبادتوں کا اجر دے گا۔‘‘
غور طلب ہے کہ بچپن کی معصومیت، جاڑے کی شدت، غسل کی اذیت اور اس میں بھی عبادت۔ ثواب و عذاب کی حقیقت۔ یہی اللہ میاں کا کارخانہ ہے جو پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس پھیلاؤ میں والدین کے علاوہ مسجد مدرسہ کے حافی جی بھی شامل ہوتے ہیں جو کارخانہ کے سب سے بڑے چوکی دار بن کر ابھرتے ہیں۔
لیکن ان کی چوکی داری، ان کی بد ہضمی، ان کے خراٹوں کے ذریعے ہی ان کا کردار متحرک رہتا ہے جو ناول کو سہارا دیتا ہے اور آخر تک قائم رہتا ہے۔
ورنہ جبران تو چھوٹا ہے۔ بچہ ہے اور معصوم ہے۔ دیکھیے اس کی معصومیت اور حافی جی کی شخصیت کو کیسے لبھاؤنے انداز میں پیش کیا ہے:
’’بکری کی میں میں اور حافی جی کے خراٹوں کی آوازیں بہت پریشان کرتی تھیں۔ بار بار ذہن بھٹک جاتا ہے معلوم نہیں آدمی خراٹے کیوں لیتا ہے اور یہ بکری پیٹ بھر کے گھاس چرنے کے با وُجود ہوں ہوں ہوں کیوں کرتی رہتی ہے۔‘‘
حافی جی کا باہر جانا اور بکری کا زور زور سے بھیں بھیں کرنا۔ بکری بے صبرا جان ور ہے اور انسان جس میں حافی جی بھی شامل ہیں کہ جس سے بکری بھی خوف کھاتی ہے اور جس میں بکری سے بھی زیادہ بے صبرا پن ہے۔ اسی طرح سفید اور کالی مرغی، ان کا تعارف بھی دیکھیے:
’’ہمارے گھر میں دو مرغیاں تھیں ایک سفید اور ایک کالی۔ سفید مرغی کے پروں پر کہیں کہیں کالے نشان تھے جیسے کسی نے پین سے اس کے پروں پر رُوشنائی چھڑک دی ہو۔ اس لیے اماں نے کالے نشان والی سفید مرغی کا نام چتکبری اور کالے پروں والی کا کلو رکھ دیا تھا اور ہم لوگ اسی پہچان کے ساتھ انھیں بلاتے تھے اور ان کی باتیں کرتے تھے۔ کلو سنجیدہ تھی وہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح قاعدے سے اور آہستہ آہستہ چلتی تھی اور زیادہ قیں قیں بھی نہیں کرتی تھی۔‘‘
بکری اور مرغی کے ذریعے انسانی فطرت اور کارخانۂِ قدرت کے جس سپید و سیاہ کہیں کہیں دونوں کی چتکبری آمیزش کے جو اشارے کیے گئے ہیں وہ محض تعارف نہیں ہیں بَل کہ معرفت اور حقیقت کے وہ پر ہیں وہ کل ہیں جس سے کارخانۂِ قدرت کا نظام چلتا ہے۔
غلط یا صحیح بکری، مرغی کی بھوک کی تو حدیں ہیں جو گھاس اور دانے تک محدود ہیں لیکن انسان کی بھوک، فتانت اور شرارت کے آگے تو بچوں کی شرارت بھی پھیکی اور معمولی ہے۔
محسن نے جس طرح بکری اور بلی کے مناظر کو پیش کیے ہیں اس سے جُزئیات نگاری، چرند پرند کی فطرت کے اچھے نمونے سامنے آتے ہیں جو اب نئے ناولوں میں مشاہدے کی کم زوری کی وجہ سے کم نظر آتے ہیں۔
اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب محض منظر نگاری یا لطفِ بیان کے لیے نہیں ہیں، بَل کہ تخلیقی وجدان کے ذریعے اصل انسان اور انسانی فطرت تک پہنچنے کا مؤثر ذریعہ بنتے ہیں اور ساتھ میں خیر و شر، شرافت و خباثت کا اظہاریہ بھی بَہ قول مصنف:
’’بچپن کی باتیں ساری زندگی انسان کے ذہن میں پا گُر ہوتی رہتی ہیں‘‘ اور یہ معنی خیز جملہ:
’’ہماری یہ مرغیاں ایک ساتھ انڈے نہیں دیتی تھیں۔ کلو انڈے دیتی تھی تو چتکبری کڑک ہو جاتی تھی اور چتکبری انڈے دینے لگتی تھی تو کلو کڑک ہو جاتی تھی۔ چتکبری میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس کا انڈا کلوا کے انڈے سے بڑا ہوتا تھا۔‘‘
غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو مرغی تیز طرار ہے، کنکالہ ہے، زیادہ چیختی ہے وہی بڑے انڈے دیتی ہے۔ جو انسان حرکت و عمل میں ہے، جبر و قدر میں ہے وہی صاحبِ اختیار ہے۔ مال و دولت سے سرشار۔ جو شریف ہے مذہبی ہے۔ نمازی ہے جیسے حافی جی انھیں صرف نماز پڑھنے پڑھانے کی سعادت ملی ہے اور کچھ نہیں۔ نیک مرغی بلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ چالاک چتکبری بچ جاتی ہے جیسے نیک لوگ خواہ مخواہ بدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
ہر طرف شکار ہی شکار۔ اسی لیے ناول سوال سے ہی شروع ہوتا ہے: ’’اللہ میاں نے مرغی کے ساتھ بلی کیوں بنائی ہے؟‘‘ نہایت اہم سوال جو صرف بلی تک محدود نہیں رہتا، بَل کہ پورے کارخانہ کو اپنی زَد میں لے لیتا ہے اور ناول سزا و جزا، ظلم و جبر کی قدروں سے ہم کِنار ہو کر اپنے بال و پَر پھیلاتا ہے اور یہیں سے ناول ناول بننا شروع ہوتا ہے تبھی تو پریم چند نے کہا تھا:
’’ناول کو اپنا مواد الماری میں رکھی کتابوں سے نہیں، بَل کہ انسانوں سے لینا چاہیے جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔‘‘
پریم چند نے تو انسانوں کے ارد گرد جان ور اور چرند پرند کو بھی لیا، گئودان میں گائے، پوس کی رات میں کتا، دو بیل سب کے سب انسانوں کی طرح بڑے کردار بن کر ابھرتے ہیں۔
اسی طرح محسن کے اس ناول میں مرغی، بلی، بکری وغیرہ ناول کا حصہ ہی نہیں اس کارخانۂِ قدرت کا کہیں تماشا اور کہیں ظلم و جبر کا نوالہ بنتے نظر آتے ہیں جیسا کہ محاورتاً کہا جاتا ہے، ’’بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگلتی آ رہی ہے۔‘‘ اور محاورے زندگی کے تجربات و حادثات سے ہی جنم لیتے ہیں جو فکشن کی عمارت سازی میں استعمال ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد میں حقائق (facts) کا آمیزہ ہوتا ہے۔
ایک فیکٹ یہ بھی دیکھیے کہ وہ نظام خانہ ہو یا اللہ میاں کا کارخانہ، چھوٹا ہو یا بڑا، پٹری ہو یا پٹرا امتیاز و اختصاص ہر جگہ ہے۔ دیکھیے:
’’ہمارے گھر میں چار پٹریاں تھیں … اماں نے نشان لگائے بغیر سب کی پٹریاں الگ کر دیں۔ جو پٹری ذرا اونچی اور چوڑی تھی وہ ابا کے حصے میں آئی۔ جو پٹری ابا کی پٹری سے ذرا نیچی مگر سڈول تھی، مجھے مل گئی۔ نصرت کو جو پٹری ملی اس کے دونوں کنارے کچھ پتلے تھے اور وہ چھوٹی سی کشتی جیسی لگتی تھی۔ اماں کی پٹری سب سے نرالی تھی وہ ایک طرف سے اونچی اور ایک طرف سے نیچی تھی۔ اس پر بیٹھ کر اما کچھ ٹیڑھی ہو جاتی تھیں۔ ابا کی پٹری ابا کے انتظار میں خالی رہتی تھی۔‘‘
مرد اساس معاشرہ کا یہ اشاریہ صرف واقعہ کو نہیں پیش کرتا، بَل کہ پٹرے کے بڑھئی سے لے کر کارخانۂِ قدرت کے کاری گر تک پھیلے تفریق و تعذیر کو پیش کرتا ہے کہ شرارت کسی اور کی اور سزا کسی اور کو۔ انگلی جبران کے کی گئی تو اس معصوم بچے نے نماز کا احترام کیا اور نیت نہیں توڑی کہ کہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو جائیں لیکن جب عابد چچا کے انگلی کی گئی تو عابد چچا نے نیت توڑ کر زور دار کنٹاپ رسید کیا اور تہذیبِ عبادت کی شکستگی و بے حرمتی کے با وُجود یہ کہتے رہے:
’’نہایت بد تمیز لڑکا ہے۔ کیا آپ نے اسے یہ تہذیب سکھائی ہے؟‘‘
لیکن شرارت اور لعنت تو ان دونوں کے درمیان کہیں اور رقص کر رہی تھی۔ یہی دنیا کا تماشا ہے کہ تماشا کچھ اور، اور تماشائی کوئی اور۔ تبھی تو ایک صفحہ پر لکھا ہوا ملتا ہے:
’’یہ دنیا ایک تماشا گاہ ہے۔ یہاں کوئی تماشا دکھا رہا ہے کوئی تماشا دیکھ رہا ہے۔‘‘
حافی جی کی خدمت اور نسرین کا یہ سوال: ’’اللہ میاں نے یہ دنیا بنائی کیوں ہے؟‘‘
حافی جی نے معقول جواب دینے کے بَہ جائے یہ کرشماتی جواب دیا:
’’یہ دنیا اللہ میاں نے صرف چھ دن میں بنائی‘‘ اور وہ بھی چھ دن اس لیے کہ دنیا بہت سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے لیکن شاعر جون ایلیا تو یہ کہتے ہیں؎
حاصلِ کن ہے یہ جہانِ خراب
یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں
لیکن بچوں کےسوال سے زیادہ بڑے شعر نہیں ہیں۔ یہیں سے ناول شاعری سے الگ بھی ہوتا ہے جب جبران سوال کرتا ہے:
’’اگر اللہ نے مرغی بنائی تھی تو بلی کیوں بنائی؟‘‘ جس کا جواب نہ حافی جی کے پاس تھا (اور نہ جون کے پاس ہوتا)۔ وہ جب بھی لا جواب ہو جاتے تو عبرت کی چھڑی استعمال کرنے لگتے۔
ناول نگار نے معصوم کم عمر طالب علموں اور کم پڑھے گئے مدرسوں کے ما بین جو مکالمات رقم کیے ہیں وہ اس قدرت فطری اور ان کی تخلیقی پیش کش اس قدر سادہ لیکن معنی خیز ہے کہ اسی سادگی اور پاگیزگی سے کِذب اور جبر کے اشارے ملنے لگتے ہیں۔ انسانی فطرت کے در کھلتے ہیں۔ یہ بات مدرسے کے حافی جی سمجھ پاتے ہیں اور نہ جماعت سے منسلک والد صاحب۔ بس ہر طرف ڈانٹ پھٹکار ہے۔ عبرت کی چھڑی اور یہ ایک انمول گھڑی:
’’(انڈوں پر مرغی) اس طرح خاموش بیٹھی رہتی جس طرح ابا اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔‘‘
دونوں عبادت گذارانہ عمل ہیں۔ ایک کا تخلیقی، دوسرے کا مذہبی۔ اسی طرح چوری کی عادت اور سپارہ کی قرأت پتنگ کی ڈوری اور جُز دان میں پوشیدگی۔ فجر کی اذان کے ساتھ کتے کی ہاؤ ہاؤ۔ ایک طرف سپارہ کا سبق یاد کرنا دوسری طرف بکری کا چلانا۔ زندہ بکری کا چرانا اور مردہ قبروں کا نظر آنا اور پھر ایک عجیب سوال:
’’کیا تمھاری بکری مسلمان ہے؟ اور کیا گائے ہندو ہوتی ہے؟‘‘
اور اس سے بڑا یہ سوال:
’’اللہ میاں کسی امیر اور کسی کو غریب کیوں بناتے ہیں؟‘‘
ماں نے جواب دیا:
’’یہ سب کچھ اپنی قسمت اور اللہ کی مرضی پر منحصر ہے!‘‘
تو پھر ایک سوال:
’’جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر ابا نے آپ کی پٹری ٹیڑھی کیوں بنوائی؟‘‘
بچوں کے معصومانہ سوال در اصل وہ عارفانہ جلال ہیں جن پر کائنات ڈگ مگا رہی ہے۔ عدم توازن کا شکار ہے۔ مرغی، بلی، بکری کے بعد بندر کا تماشا ہے، پتنگ بازی ہے جس سے ناول کی قرأت میں عام سی دل چسپی ضرور پیدا ہوتی ہے لیکن تماشوں کے درمیان بعض مکالمے زندگی کی رمزیت کی طرف لے جاتے ہیں مثلاً:
’’تم اپنی پتنگ کو اتنی ہی اونچائی تک لے جا سکتے ہو جتنی ڈور تمھارے پاس ہے۔‘‘
’’تم بھوکی ہو اس لیے تم کو کھیل اچھا نہیں لگ رہا ہے۔‘‘
’’تم کو پتا ہے کہ پیٹ پوجا کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔‘‘
’’تماشائی ایک تماشا دیر تک نہیں دیکھتے۔ اب کوئی دوسرا تماشا دکھاؤ۔‘‘
بَہ ہر حال، پتنگ بازی، بندریا کا رقص، بھوک پیاس، امیدیں آرزوئیں، سچ جھوٹ کا ملغوبہ زندگی کا تجربہ اور حافی جی کا غصہ، ان سب کو سمیٹتا ہوا ناول تنی ہوئی رسی پر تماشے کی طرح آگے بڑھتا ہے اس ہدایت کے ساتھ:
’’رسی پر چلنے کا تماشا دکھاتے وقت تماشائیوں کو دیکھو گے تو گر جاؤ گے۔‘‘ کم و بیش یہی عمل ناول نویسی کا بھی ہوتا ہے کہ ناول نگار نے ناول نگاری کی فطری تخلیقی اور کسی ہوئی رفتار سے نگاہ ہٹا کر ادھر ادھر کی قارئین و ناقدین کے بارے میں سوچا تو ناول کرشمہ ساز لڑکی کی طرح عدم تعاون کا شکار ہو جائے گا اور نٹ کی طرح ناول بھی مُنھ کے بَل گر پڑے گا۔
حافی جی بھی پتے کی بات کہتے ہیں:
’’یہ دنیا ہے۔ یہاں کوئی ہوا میں اُڑ رہا ہے، کوئی پانی پر چل رہا ہے، کوئی رسّی پر چل رہا ہے۔ یہ شعبدے بازیاں یہیں دھری رہ جائیں گی۔ جب اللہ کے گھر جاؤ گے اور پل صراط پر چلنا پڑے گا تب حقیقت معلوم ہو گی۔‘‘
نٹ کی رسّی اور ناول نویسی تو متوازی تھی۔ رسّی پر چلنا اور پل صراط پر چلنا بھی متوازی ہو گئے۔ لیکن دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم الگ الگ ہو گئے۔ والد قرآن سینے سے لگائے ہیں، بچوں کو ایک بار بھی سینے سے نہیں لگایا۔ حافی جی کے ہاتھوں میں عبرت کی چھڑی ہے اور والدہ یعنی عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔
اس کے تو ہاتھ ہی جلتے ہوئے برتن دھوتے دھوتے سُن ہو گئے ہیں۔ بل کہ پورا بدن ہی سُن ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ اس کی تقدیر کی طرح اس کی پٹری بھی ٹیڑھی ہے جس نے پوری زندگی کو سُن کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ان کا سُن اور سناٹا ہی ان کے کردار کو جگائے رکھتا ہے ساتھ ہی ناول کو بھی۔
ناول میں جو کردار مرکزی ہوتے ہیں زیادہ بولتے ہیں۔ وہ اکثر متأثر نہیں کرتے۔ لیکن خاموش کردار کی کش مکش، صبر و تحمل کی کشاکش اس جلتے ہوئے توّے کی طرح ہوتی ہے جس میں پانی کی چند بوندیں پڑتے ہی چھن سی آواز ہوتی ہے پھر دھواں اٹھنے لگتا ہے لیکن یہ دھواں، یہ غبار، یہ چھن کی آواز ہی ناول کو بلند آہنگی عطا کر جاتی ہے الجھاوے ناول کو سلجھاتے چلتے ہیں۔ ان جملوں کو دیکھیے:
’’نصرت چراغ کی روشنی میں بڑے لوگوں کی کتاب پڑھ رہی تھی اور میں اپنی وہ ڈور سُلجھا رہا تھا جو جلدی جلدی کھینچنے کی وجہ سے الجھ گئی تھی۔ اب میں ان گرہوں کو توڑ کر چھوٹی گرہیں لگا رہا تھا۔‘‘
اور یہ جملہ:
’’الجھی ہوئی ڈور کو سہولت سے نہ سلجھایا جائے تو زیادہ اُلجھ جاتی ہے اور اسے توڑ کر گانٹھیں لگانی پڑتی ہیں۔‘‘
یہ محض جملے نہیں محاورے بھی نہیں بَل کہ تجربے ہیں اور جو آگے بڑھ کر زندگی کے فلسفے بن جاتے ہیں۔ ان فلسفوں کے بارے میں ضروری نہیں کہ مصنف اپنی رائے بھی پیش کرتا ہے۔ کرداروں کے عمل، ردِ عمل ٹکراو اور پھیلاؤ سے زندگی کی صحیح اور سچی تصویر اس کی تخلیق میں نظر آنی چاہیے اس لیے کہ ایک عمدہ ناول انسانی تجربوں کے امکانات کا پتا لگاتا ہے، شعور کے نِہاں خانوں کو ٹٹولتا ہے، جذبات و خیالات کی پیچیدہ تاریک اور دشوار گذار راہوں کو منور کرتا ہے؛ فرد اور سماج کے تعلقات کی نازک گتھیوں کو سلجھاتا ہے؛ حیات و کائنات کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتا ہے اور کبھی کبھی انمول اور انجانے موتیوں کو تلاش کر لیتا ہے۔
مایا کوفسکی نے غالباً اسی لیے ناول کو “a ourney to the unknown” کہا ہے۔ ممتاز ناول نگار اقبال مجید نے بھی کہیں لکھا ہے کہ ناول نا گہانی آبگینوں کا متمنی ہوتا ہے۔ ایک عمدہ ناول آبگینوں سے ایسے ہی نکلتا ہے جیسے کالی مرغی کے انڈے سے سفید چوزے نکلتے ہیں جو بَہ ظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن والدہ کی زبان میں:
’’جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کی چال ڈھال میں فرق آئے گا۔ کوئی تیز دوڑے گا کوئی دھیرے دوڑے گا۔ کوئی جلدی جلدی دانا کھائے گا۔ کوئی اطمینان کے ساتھ کھائے گا۔ کوئی ڈرپوک ہو گا تو کوئی لڑاکو۔ کوئی نصرت کی طرح سمجھ دار ہو گا اور کوئی تمھاری طرح بے وقوف۔ بس ان کی عادتوں سے ہم انھیں پہچان لیا کریں گے۔‘‘
یہ بڑی باتیں تجربہ کار و وفا شعار درد مند والدہ ہی کہہ سکتی ہیں؛ نہ والد نہ حافی جی۔ والد کی سوچ جماعت کی سوچ ہے اور حافی جی کی سوچ میں بد ہضمی ہے وہ رحل سپاروں اور بچوں کے بیچ و بیچ گیس چھوڑتے رہتے ہیں۔ کھٹی کھٹی ڈکار لیتے رہتے ہیں اسی لیے ان کی سوچ میں بھی کھٹاس اور ڈکار ہے۔
ناول ہلکی سی کروٹ لیتا ہے اور ایک بڑے بنیادی سوال سے ٹکراتا ہے اور وہ یہ کہ جب والد جماعت میں جانے لگے تو والدہ نے پوچھا:
’’گھر کیسے چلے گا؟‘‘ ’’اللہ چلائے گا!‘‘ یہ جواب تھا مرد کا۔ ٹوٹی چپل، والدہ کی بیماری، گھر کا خرچہ اور اللہ میاں کا کارخانہ۔ وہ کارخانہ تو چلا سکتا ہے لیکن گھر چلانے کے لیے تو مرد کو بھی اللہ میاں نے متعین کیا ہے (*** … ناول کی اندرونی دنیا کے ضوابط نے، کسی با ضابطہ کائناتی حقیقت نے نہیں… مدیر ایک روزن) لیکن وہی مرد جب بار بار یہ کہے، ’’اللہ چلائے گا‘‘ تو اس کی مردانہ و ذمے دارانہ معنی و مفہوم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سارے کام جو انسانوں کے کرنے کے ہیں وہ انھوں نے اللہ پر چھوڑ دیے ہیں اور جو کام اللہ کا ہے وہ حافی جی اور والد جیسے مردوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔
اسی طرح مرغی کا تتلی کھانا، بلی کا مرغی کھانا، بکری کو بھیڑیے کا کھانا، یہ سب نظام جبر و قدر کے ایسے عناصر ہیں جو بچوں کے معصومانہ اور انکشافانہ عمل کے ذریعے شروع ہوتے ہیں اور عارفانہ عمل پر ختم ہوتے ہیں؛ جب کہ نہ اس میں وعظ ہے نہ نصیحت و فلسفہ۔
پریم چند نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ وعظ، نصیحت، فلسفہ وغیرہ عالموں فاضلوں کے لیے ہوتا ہے۔ ناول عوام کے لیے ہوتا ہے جو عوامی کرداروں، مکالموں کے ذریعے خواص تک پہنچتا ہے۔ کرداروں کی مشکلات و تصادمات اور ان کے بطن سے پھوٹتا ہوا فلسفۂِ حیات ہی ناول کو بڑا بنا تا ہے۔
بَہ ظاہر جبران کا کردار شرارتی ہے۔ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا تاہم ناول نگار نے اس کی شرارت میں معصومیت اور معصومیت میں ایسی حقیقت بھر دی ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ناول سپاٹ اور شریف کرداروں سے بڑا نہیں ہوتا؛ ناول بڑا ہوتا ہے ٹکراؤ سے، تناؤ سے، پھیلاؤ سے، جو کرداروں اور مکالموں کی روحانی تلخیص و تعبیر میں پوشیدہ رہتا ہے۔
کردار انسان بھی ہوتے ہیں حیوان بھی اور جبران بھی۔ ایک عرصہ کے بعد ایسا ناول پڑھنے کو ملا ہے جس میں انسان کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی مرغی، بلی، بکری جیسے حیوان کی بھی۔ دونوں متوازی طور پر ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور فلسفۂِ حیوانات کی نئی نئی تعبیریں پیش کرتے ہیں جس سے ناول دل چسپ، پُر کشش اور لائقِ مطالعہ ہو جاتا ہے۔ ناول میں تھوڑی دیر کے لیے تتلی ایسے ہی آتی ہے جیسے قلندر بابا آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن ایک نقش چھوڑ جاتے ہیں۔
ساتھ ہی زندگی کا ایک روّیہ بھی، تتلی شکار ہو جاتی ہے اور بابا رُو پوش۔
ناول تتلی کے رنگوں اور چوزوں کے پروں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے جس میں بکری ہوں ہوں بھی شامل ہے۔ رنگوں، پَروں اور ہوں ہوں کا حال تو بس اللہ میاں ہی جانتے ہیں انسان صرف دیکھ اور سن سکتا ہے کہ مرغی کو بلی کھا گئی، تتلی کو مرغی کھا گئی اور بکری کھا کھا کر بھی ہوں ہوں کرتی ہے اور انسانی فکر و عمل اس کی تبلیغ و ترغیب کرکے بھی بھوکا رہتا ہے، بچے بھوکے رہتے ہیں۔
بینُ السُّطور یہ سوال بار بار سر اٹھاتا ہے جو اللہ کے جمال اور جلال سے راست طور پر رشتہ رکھتا ہے لیکن اللہ سے لو لگانے والے بہ صورتِ دیگر دنیاوی ذمے داری سے مُنھ چرانے والے اس سوال سے کتراتے ہیں لیکن ناول نگار نہیں کتراتا۔
یہی فرق ہے ناول نگار میں اور عبادت گذار میں۔ اسی لیے لارنس ناول نگار کو بڑا مقام دیتے ہوئے صوفی سَنّت سے آگے لے جاتے ہیں۔ مولوی کہتا ہے کہ اللہ رمضان میں مؤمنوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سچ ہو، لیکن ناول نگار رزق نہیں پیش کرتا وہ بھوک پیش کرتا ہے۔ اسی لیے کوئی اور نہیں وفا شعار پرہیز گار بیوی کہتی ہے:
’’بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ بیوی بچوں کو اللہ کے سہارے چھوڑ کر چلے گئے (تبلیغ کرنے) صاف صاف بتا کر بھی نہیں گئے کہ کب لوٹیں گے۔‘‘
یہ ہے جماعت اور یہ ہے عبادت کہ حاملہ بیوی پریشان، بچے بھوک سے ہلکان اور مسجد میں وعظ ہو رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رزق بڑھ جاتا ہے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں لیکن پیٹ کا دوزخ تو کبھی بند نہیں ہوتا خواہ وہ مقدس ماہِ رمضان ہی کیوں نہ ہو اور بھوکے پیٹ تو عبادت بھی نہیں ہوتی چِہ جائی کہ امام صاحب کی طولانی تقریر جس میں امام صاحب مسلمانوں کی سلامتی اور راستی کی دعا مانگ رہے تھے اور جبران کے والد بھوکے بیوی بچوں سے بے نیاز خدمتِ مذہب میں مصروف تھے۔ ایسی تقدّس بھری مصروفیت کہ بیوی بچوں کی یاد تک نہیں آتی اس لیے بچے کی دعا امام صاحب کے دعا سے مختلف ہے۔
امام صاحب کی دعا میں ضرورت تھی اور بچے کی دعا میں فریاد؛ کہ چوزے مرغی سب جی اٹھیں اور بلی مر جائے۔ حافی جی کا تبادلہ ہو جائے اور ماں کے ہاتھ میں کنگن آ جائے، اور ابا گھر لوٹ آئیں۔ ان کا گھر لوٹ آنا سب سے بڑی ضرورت اور غالباً سب سے بڑی عبادت۔ اور پھر یہ معصومانہ احساس:
’’دعا مانگنے کے بعد میں نے سوچا معلوم نہیں اللہ میاں نے امام صاحب کی اتنی دعاؤں کے بعد میری دعائیں بھی سُنی ہوں گی یا نہیں اور اگر سنی بھی ہوں گی تو پتا نہیں انھیں یاد بھی رہیں گی یا نہیں یاد رہیں گی۔‘‘
اسی سے ناول میں درد مندی پیدا ہوتی ہے اور دل کشی بھی۔ دو قسم کی دعاؤں سے۔ دعاؤں کے کراس سے جو زندگی کے برہنہ تضاد سے بے رحم رشتہ رکھتا ہے۔ یہ برہنگی اور بے رحمی ہی رزمیہ ہے اور ناول مہا رزمیہ۔ اللہ میاں کا کارخانہ بھی تو مہا رزمیہ ہے اور محسن بڑے سلیقے اور سادگی سے اس رزمیہ کو شفاف بیانیے میں پیش کرتے چلے جاتےہیں: تتلی کا رنگین پر، چوزوں کے سفید پنکھ اور تیتر کے سرخ پر یہ سب رمزیہ تخلیق کے فن کارانہ اشارے ہیں جس سے ناول رنگین پروں پر تتلی کی طرح اڑتا چلا جاتا ہے۔
دہشت گردی کے شک میں باپ کی گرفتاری، مسجد میں ہاتھا پائی، بکری کا مسلمان اور گائے کا ہندو ہونا، والدہ کا پریشان ہو کر وظیفہ پڑھنا ان سب کے ذریعے ناول ایک بچے کی معصومیت سے نکل کر سماج کی خارجی حقیقت سے رشتہ بناتا ہوا اپنے پلاٹ کو بڑا کرتا ہے کہ مصائب و مسائل جتنے بڑے اور پیچیدہ ہوں گے ناول کا کینوَس از خود بڑا ہوتا چلا جاتا ہے سچ تو یہ ہے کہ ناول کا اصل کارخانہ بھی وہی ہے جو اللہ میاں کا کارخانہ ہے۔ ناول کے اگلے حصے میں پولیس، وکیل، تھانہ سبھی آنے لگتے ہیں اور پھر یہ جملہ:
’’جب انسان پر بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ چھوٹی پریشانیاں بھول جاتا ہے۔‘‘
اب اس کا کیا کیا جائے کہ اس پھیلاؤ اور ٹکراؤ سے ہی ناول کی تخلیق ہوتی ہے۔ رزمیہ سے ہی بزمیہ بنتا ہے۔ اب پولیس ہے، تلاش ہے، گرفتاری ہے، والد کو تو گرفتار کیا ہی گیا ساتھ ہی بچوں کے سپارے اور معصوم آنکھوں کے شرارے بھی گرفتار کر لیے گئے۔
ناول کی پاکیزگی بھی روٹھ گئی نا روا ظلم کا شکار ہو گئی لیکن اگر ناول کو قصے سے اوپر اٹھ کر فلسفہ بننا ہے تو یہ سب ہونا ہی ہے، بَل کہ یہ کہا جائے کہ یہی زندگی کی اصل تصویر ہے اور ناول کی تخلیق۔ ناول تو صرف اس کا آئینۂِ معکوس ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک جگہ رال فاکس نے کہا تھا:
’’ناول میں زندگی سے متعلق مصنف کی رائے درکار نہیں، بل کہ زندگی کی صحیح اور سچّی تصویر نظر آنی چاہیے۔‘‘
انھوں نے یہ بھی کہا تھا:
’’ناول صرف افسانوی نثر نہیں، بل کہ یہ انسانی زندگی کی نثر ہے۔ یہ وہ پہلا فن ہے جس نے پورے انسان کو پیشِ نظر رکھنا اور اسے زبان عطا کرنے کی کوشش کی۔‘‘ اور یہ انگریزی کا جملہ:
“The novel is the epic art from our bourgeois society.”
یہ زندگی کا متضاد و متصادم المیہ اور رزمیہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے پر گیا اللہ نے اُسی کو گرفتار کروا دیا۔ لیکن اللہ غلط کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ تو اللہ ہے کہیں نہ کہیں انسان ہی غلط ہے جو اپنی حاملہ بیوی کو تڑپتا اور معصوم بچوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر دعوتِ دین دینے نکل گیا اور اپنے اصل فرائض کو بھول گیا اس لیے نہ دین کا رہا نہ دنیا کا۔ یہی انسان کا کارنامہ ہے اور یہی اللہ میاں کا کارخانہ۔
ناول میں ایسے رزمیے اشاروں اشاروں میں قدم قدم پر پیش کیے گئے ہیں جن سے واقعات کی ترتیب بنتی ہے ناول کا فطری و فکری ارتقاء بھی۔ وارث علوی نے ایک جگہ لکھا ہے:
’’ایک اچھے ناول میں واقعات اینٹوں کی طرح چُنے ہوتے ہیں کیوں کہ سب سے پہلے وہ اپنے حسنِ تعمیر سے ہی متأثر کرتے ہیں۔‘‘
اس حسنِ تعمیر و تخلیق کے سلسلے میں ابتداء میں ہی عرض کیا تھا کہ تخلیق و تنقید خواہ کتنی ہی ترقی کر جائے، بدل جائے لیکن وہ کچھ بنیادی عناصر سے الگ نہیں ہو سکتی جس میں اولین شفاف بیانیہ ہے جو علامتی بیانیہ بننے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے؛ معنی خیز اور فکر انگیز نَیریشن (narration) کے بَہ غیر ناول ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے لیے واقعہ کا تخلیقی تجربہ میں ڈھلنا۔ اور فن کارانہ بیانیے میں پیش ہونا ہی ناول کا اصل فن ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ناول لکھنا شعر کہنے سے بالکل الگ ہے۔ وارث علوی نے یہ بھی کہا تھا کہ شاعری تو آدھی زمین سے اوپر ہوتی ہے اور آدھی نیچے لیکن ناول خالص زمین کی چیز ہوتا ہے۔ یوسا نے ناول کو جھوٹ کا نام دیا ہے۔ شاید اسی لیے اس کو فکشن کہا جاتا ہے؛ لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں:
’’یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کے پیچھے ایک گہری سچائی چھپی ہوتی ہے۔‘‘
گویا کہ ہمارا اصل سروکار اس سچائی سے ہے جو کسی با معنی انسانی صورتِ حال سے ہوتی ہے اس کے حجاب سے نہیں۔ ممتاز اردو نقاد شمیم حنفی نے بھی کہا تھا:
’’تکنیک کا کام نئے دروازے کھولنا ہے، پُرانے دروازے بند کرنا نہیں اور راستوں پر پہرے بٹھانا نہیں۔‘‘
اس ناول میں روایتی بیانیہ، قصہ خوانی، پریشانی، دادی نانی بہت کچھ پرانا ہوتے ہوئے بھی بالکل نیا نیا سا ہے جو شفاف اور سادہ اسلوب، کردار نگاری یہاں تک کہ جزئیات نگاری کی جو روشِ قدیم ہے اس کی قدامت میں جدیدیت ہے۔ وہ کبھی پرانی ہو ہی نہیں سکتی۔
اس لیے کہ جو اسلوب زندگی کا ہے وہی ناول کا ہے اس لیے اسلوبِ تخلیق کو سمجھنے کے لیے اسلوبِ حیات کا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس اسلوبِ حیات ہو گا تو مقصدِ حیات بھی ہو گا اور مقصدِ حیات ہو گا تو مقصدِ ادب بھی ہو گا اور مقصدِ ادب ہے تو مقصدِ زندگی کے سرے خواہ کتنے ہی الجھے ہوئے ہوں سلجھتے چلے جائیں گے۔
والد کا گھر نہ لوٹنا، پولیس کا گرفتار کرنا، بچے کی نفسیات بدل دیتے ہیں۔ ایک جملہ دیکھیے:
’’اللہ میاں نے ہماری کوئی دعا نہیں سنی اس لیے میں ان سے ناراض تھا اور نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا۔‘‘
یہ معصوم ناراضی، پولیس کی بے رحمی، ممتا کی بے چارگی جہاں بچے مرغی کے چوزوں کو بھول گئے، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، بکری چرانا شروع کر دیا، یہ ہیں زندگی کے انقلابات۔ یہ ہے زندگی کا کارخانہ جس کے مالک و مختار ہیں اللہ میاں جس کے سامنے ہم سبھی سجدہ کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں لیکن بے رحم زندگی تو اپنے حساب سے چلتی رہتی ہے۔
لیکن یہ بے رحمی انسان کی ہے یا اللہ میاں کی ہے معصوم جبران کی سمجھ سے باہر ہے لیکن ذہین قاری تو سمجھتا چلتا ہے کہ یہ سب تو حضرتِ انسان کے کرشمے ہیں، کارنامے ہیں۔ یہی زندگی ہے اور زندگی کا کارخانہ اور یہی ہے ناول اللہ میاں کا کارخانہ۔
محسن خاں نے پورے ناول کو پیچیدگی میں سادگی، اور سادگی کو گہرائی میں پیش کر کے اردو کے نئے ناول نگاروں کے سامنے بہت سارے در کھول دیے ہیں اور درس بھی دے دیے ہیں کہ ناول کا اسلوب، ناول کا بیانیہ جس قدر سادہ اور دل کش ہو گا اتنا ہی زیادہ پڑھا اور پسند کیا جائے گا۔
بیانیے کا حسن یہی ہے کہ وہ آلودگی میں پاکیزگی رزمیے میں، بزمیے اور المیے میں طربیے کی راہ تلاش کرے۔
ناول کی تخلیقیت، بُقراطیت، مرعوبیت کی محتاج نہیں اور نہ ہی اسے شعورِ علم کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ ناول نویس شعوری علم سے زیادہ شعورِ کائنات سے ہم کنار ہوتا ہے؛ وہ سادگی میں پیچیدگی اور پیچیدگی میں سادگی کے کراس سے اپنا ڈھانچہ تیار کرتا ہے۔
ہربرٹ ریڈ نے کہا تھا کہ تنقید تو خود ایک تخلیق ہوتی ہے تخلیق در تخلیق۔ یہ ناول خدا کی بستی، ٹیڑھی لکیر، گئو دان کی ایک مختصر لیکن بے حد مؤثر، کام یاب توسیع ہے اور یہ توسیع بھی اپنے آپ میں ممتاز و منفرد ہے اس لیے کہ قابلِ قدر و غور طلب وسعت اس کی انفرادیت کو متأثر نہیں ہونے دیتی۔
زندگی کی طرح ادب کی روشنی بھی چراغ در چراغ پھیلتی ہے اور اللہ کے کارخانے کو روشن کر جاتی ہے۔ اس روشنی کے لیے محسن خاں کو جتنی بھی مبارک باد دی جائے کم ہے کہ اس سے کم از کم ناول کا کارخانہ تو روشن ہوتا ہی ہے اللہ میاں کا کارخانہ تو جیسے چلتا رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا۔