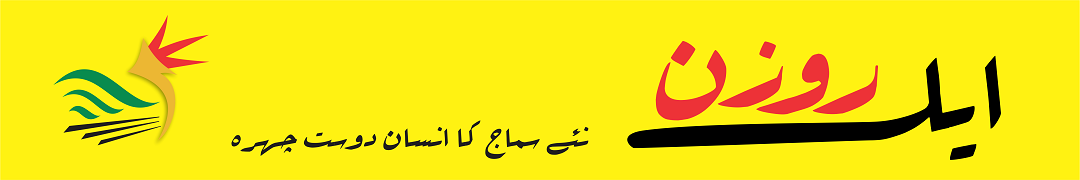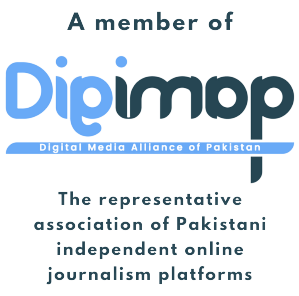بریشم کی طرح نرم (بیادِ استادم رفیع الدین ہاشمی)
از، ڈاکٹر ارسلان راٹھور
اورینٹل کالج کا کتاب خانہ، مغربی دریچوں سے غروب ہوتی شام کا منظر!کہرے کے نم گیرے مستحکم ہو چلے تھے۔ شاہانہ بے نیازی ان وقتوں میں خاص شعار تھی، میں دیوان حماسہ کی شرح، توضیح الدراسہ پکڑے کتاب خانے سے نکلنے ہی کو تھا کہ دہنے ہاتھ میز پر بیٹھے شریف لیکن طرفہ وضع کے بزرگ آدمی نے متوجہ کر لیا۔ جسم نزار، نقوش باریک، بدن املتاس کی شاخ، سر پر بھوری جناح کیپ، ٹوپی کی لمبائی نے چہرے کو بھی طولانی ہیئت بخش دی تھی۔ ضعف سے ہنسلی کی ہڈی کمان دکھائی دیتی تھی۔
مجھے یزید بن عبد الملک کی محبوب کنیز حبّابہ یاد آ گئی، جو اپنی جادوئی آواز میں یہ شعر گایا کرتی:
بین التراقی و اللھاۃ حرارۃ
ماتطمئن و لا تسوغ فتبرد
”ہنسلی کی ہڈی اور حلق کے کوّے کے درمیان ایک آتشِ سوزاں ہے جو نہ سکون پذیر ہوتی ہے اور نہ نگلی جا سکتی ہے تاکہ ٹھنڈی ہو جائے“۔
منحنی ہاتھوں سے سرخ پنسل تھامے لکھنے میں محو ہیں، پنسل بھی وہ جسے بازار میں دیکھے ایک زمانہ ہو چلا تھا۔ بَر میں سفیدنرم سوت کے کپڑے، سادہ اور کسی قدر ملگجے، غالباًاپنی طبیعی عمرپوری کر چکے تھے۔ بھوری صدری کے دونوں جیب شذروں اور پرزوں سے بھرے، سینے کی بائیں جانب چار پانچ قلم سجائے، کلائی میں راڈو کی ساعت! آنکھوں میں حسرت موہانی کا نقشہ پھرنے لگا۔
قریب دیکھ کر بیٹھنے کو کہا، لہجہ بے حد آہستہ، قدرے زکام زدہ لیکن آواز کی پستی میں نقاہت سے زیادہ احتیاط کا پہلو نمایاں۔ غور کیا تو ایم فل، پی ایچ ڈی کے مقالوں کی بوسیدہ فہرست کی تصحیح کیے جاتے ہیں۔ غلطیوں میں غلطاں کفِ افسوس ملتے ہیں۔یقینا ً وہ اس کام پر معمور نہ تھے لیکن ذوق نے لگام ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ دیوان ِ حماسہ دیکھ کر مسکرائے۔شہر کا نام پوچھا، میں نے بتایا: ”چکوال“۔ میرا جواب سنتے ہی خفیف لیکن گہری مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی۔
یہ دسمبر۲۱۰۲ء کی شام تھی۔باتیں کرتے کرتے میرے ساتھ کتاب خانے سے باہر آگئے۔گفت گو میں کھلا کہ وہ بھی تلہ گنگ سے علاقہ رکھتے ہیں۔ چکوال سے ان کے تعلق کا سن کر میں قدرے بے تکلف ہو چلا تھا، بسا اوقات نا آشنائی بہت سی فکروں سے آزاد کر دیتی ہے، میں نے نام پوچھا، مسکرائے اور کہا: رفیع الدین۔ان کی مسکراہٹ کے ہزار پہلو تھے، میرے چہرے کو سوال بنتا دیکھ کر کہا: عرصہ ہو چلا ہے جب کسی نے یوں اخلاص اور نا آشنائی سے میرا نام پوچھا ہے۔ طبیعت خوش ہوئی، میاں خوش رہو۔ مصافحہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ کتاب دار بشیر نے بتایا کہ یہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی ہیں۔ رفیع الدین۔۔۔ہاشمی۔۔۔ نام سنا سنا تھا، اچانک یاد آیا ہمارے ہر دل عزیز استاد اور شاعر سعید اکرم صاحب کی نعتیہ کتاب پر ان ہی کا تو مضمون تھا، واہ! ملاقات کی عمدہ سبیل نکل آئی۔ یہ مرحوم سے پہلی ملاقات تھی تب سے اب تک درجنوں ملاقاتیں رہیں لیکن پہلی شام کا تاثر نقش رہا۔
میں ہاشمی صاحب کا رسمی طالب علم نہیں رہا، مجھے اس کا زیادہ افسوس بھی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ وہ گفتار کے نہیں کردار کے غازی تھے۔ ان کا اسلوبِ تدریس ایسا تھا کہ اس میں تصنع اوربے تکلفی کو دخل نہ تھا۔رعب اور بے جا خوف کے تو وہ قائل ہی نہ تھے، لیکن ان کی شخصی متانت اور بے لوث ارتکاز کا احترام ہر دل میں رہتا۔
ہاشمی صاحب ناقابلِ بیان حد تک مصروف رہنے والے لوگوں میں سے تھے، سچ میں: من المھد الی الحد کی تفسیر۔ میں نے گزشتہ چودہ برس میں ایک لمحے کے لیے انھیں ذہنی فراغت میں نہیں دیکھا۔ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ وہ انگریزی شعر کا حوالہ بہت کم دیتے تھے، لیکن خالی الذہن رہنے کے حوالے سے وہ معروف انگریزی شاعر آئزک واٹس کا مترجمہ مصرع پرھتے تھے:
”بے کار دماغوں کوشیطان برے کاموں میں پھنسا ہی دیتا ہے۔“
واٹس انگریزی کی مذہبی شعر ی روایت کا آدمی ہے، دیکھیے ہاشمی صاحب نے مصرع یاد بھی رکھا تو اپنے مطلب کا؛ کبوتر با کبوتر، باز با باز۔
کثرتِ کار سے اکثر ان کی صحت ڈاواں ڈول رہتی۔ جوانی میں ٹی بی کے باعث ایک پھیپھڑا ناکارا ہو گیا تھا، مجموعی صحت کو اس کا سخت نقصان پہنچا؛ بیماریوں کے خلاف مدافعت گویا آدھی ہو گئی۔ آدھا ادھورا کام انھوں نے اپنی عالی ہمتی سے پورا کر لیا:”بلند حوصلے عالی جناب رکھتے ہیں“۔میر کا معروف شعر سبھی کویاد ہے:
لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام
آفاق کی اس کارگہِ شیشہ گری کا
سچ پوچھیے تو ہاشمی صاحب کا حزم اس شعر کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔
سن سولہ یا سترہ کے جاڑے کا قصہ ہو گا، سخت بیمار پڑ گئے۔ کچھ دن ٹھہر کے میں عیادت کے لیے گیا۔ ان کا ضعف دیکھ کر پریشان ہو گیا، لیکن خود ہاشمی صاحب کمال بے نیازی سے ہاتھ میں دستی عدسہ لیے، اپنے سے دونی کتاب پڑھنے میں مگن تھے۔ ان کی نگرانی میں کام کرنے والا ایک اسکالر بھی وہیں بیٹھاتھا، کہنے لگا ”سر کچھ دن کام اور کتاب سے مکمل کنارا کیجیے۔“ پہلے تو اس کی طرف اپنی مخصو ص معصومیت سے دیکھا، پھر نہایت آہستگی سے کہنے لگے”اگر آپ کے مشورے پر عمل کرتا تو زندگی میں کچھ بھی نہ کر پاتا۔“
ہاشمی صاحب بتاتے تھے کہ بیماری یاخراب حالات انھیں مزید کام کرنے پراُکساتے تھے۔ اس مَد میں ان کی دلیل بڑی عجیب لیکن دل کو چھو لینے والی تھی۔کہتے: اتنے پہاڑ جھیل کر بھی ہم اگر زندہ رہنے پر آمادہ ہیں تو سخت نقصان ہے کہ بے کار جیے جائیں۔ کیسی خوب صورت بات ہے! زندگی اصل میں اپنے آپ کو کسی مضبوط دلیل کی پناہ میں دینے کا نام ہے،ہاشمی صاحب کی پناہ توانا بھی تھی اور افادہ بخش بھی۔
ملاقات سے یاد آیا، ان کے منصورہ والے گھر کا نقشہ بھی عجیب تھا، اسے گھر سے زیادہ کتابستان کہنا چاہیے۔ مہمان خانہ،جو دن رات ملنے والوں کا مرکز تھا، خود ہاشمی صاحب کی نشست گاہ بھی تھا۔ ظاہری زیبائش و آرائش سے یک سر خالی۔ وصال سے کچھ عرصہ ادھر تک اس کمرے کی ہیئت بھی عجیب تھی:مشکل سے ایک مرلے کے اس کمرے میں آدمیوں کے لیے شاید ہی دوسے تین کرسیاں بچھائی جا سکتی ہوں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کمرے میں ہاشمی صاحب کے سمیت کبھی چار لوگ بھی موجود رہے ہوں۔ ہاشمی صاحب خود موحد سہی لیکن کمرے کی اعدادی گنجائش میں تثلیث رو بہ عمل رہتی۔
قدِ آدم الماریوں میں یہاں سے وہاں کتابیں ہی کتابیں۔الماریوں کی ترتیب ایسی کہ چاروں دیواروں کے علاوہ، درمیان میں بھی الماریاں کھڑی کر کے گزرگاہیں بنا لی گئی تھیں۔ اس راہ کی تنگی سے صرف کشادہ ظرف ہی گزر پاتے۔ مشرقی کونے میں کتابوں سے گِھری بوسیدہ کرسی تھی، جس کے پاؤں میں جائے نماز بچھی رہتی، ہاشمی صاحب وہیں بیٹھ کر کام کرتے؛ ہمہ وقت و نگران۔فرض کیجیے اگر آپ ہاشمی صاحب سے ایک حد تک بے تکلف ہیں اور پہلوٹھی کمرے میں کھلنے والے دروازے کی طرف جھانک سکتے ہیں تو وہاں دھری لکڑی کی چوکی ضرور آپ کی نظر سے گزری ہو گی۔چوکی پررُوپہلی بسمے میں لپٹا مصحف پڑا رہتا،ساتھ ہی ایک رحل بھی رکھی ہوتی۔
اکل و شرب میں ناقابلِ یقین حد تک سادگی تھی۔ ان کے ملاقاتیوں میں ملک بھر کے نام ور لوگ تھے۔ وہ سب کے ساتھ اپنی فطرت کے مطابق پیش آتے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر پشاور سے تشریف لائے کسی بڑے حکومتی افسر سے ملاقات ہوئی۔ خوشی ہوئی کہ موصوف بھی کتاب خانے میں ویسے ہی سادگی سے بیٹھے تھے، جیسے کوئی اجنبی شائق۔ میرے سامنے ان کی تواضع دو چپاتیوں اور تازہ پکائی ہوئی سبزی سے ہوئی۔
ہاشمی صاحب کی اپنی پرہیزی زندگی قابلِ نمونہ تھی۔ عام دل جگرکا آدمی ان کے اصولوں کے ساتھ ایک گھنٹہ نہ ٹھہر پاتا۔ ان کے جزدان میں دو چیزوں کا ہونا لازم تھا: پانی کی بوتل اور چھوٹے سے باسن میں بندھا گھر کا کھانا۔یہ معمول ایسا سخت تھا کہ میں نے اس میں انحراف نہیں دیکھا۔ پانی کی بوتل ہر گز ہزگز نمکیاتی(Mineral water) نہ ہوتی کہ اس پانی سے انھیں نفور تھا، سادہ لیکن گھر کا پانی ساتھ رکھتے۔یہی حال بھوجن کا بھی تھا، گھر کی معمولہ سبزی یا دال۔گوشت بہ امرِ مجبوری کھاتے، لیکن مرغوب نہ تھا۔ ان کے ایک عزیز نے بتایا کہ ان کا یہ قاعدہ رسمی جلسوں میں بھی نہ بدلتا حتیٰ کہ جامعہ کی ایک تقریب میں، جس میں ظہرانہ متعین تھا، ہاشمی صاحب اپنے توشے ہی سے متلذذ ہوئے۔
کھانے پینے میں اس احتیاط پسندی میں ان کی صحت کی خرابی کے علاوہ طب سے واقفیت بھی تھی۔ میرے علم میں نہیں کہ انھوں نے یونانی طب کی کوئی باقا عدہ سند حاصل کی یا نہیں، لیکن مشرقی تمدن میں گندھے ہر کریم النفس آدمی کی طرح وہ طب کی مروجہ اور اہم کتابوں سے واقف تھے۔ ایک بار نجم الغنی رام پوری کی”تاریخ اودھ“ پر گفت گوکے دوران انھوں نے ”خزینتہ الادویہ“ پر ایسی لامع بحث کی کہ کئی نکتے روشن ہو گئے۔میں تو ظاہر ہے اس فن سے لا بلد ہوں لیکن انھوں نے یونانی ادویہ مفردہ اور طبِ یونانی کی سرگزشت(نیر واسطی) ایسی بڑی کتابوں کے حوالے دیے۔ بہت بعد میں، جب میں نظیر اکبر آبادی کے کلیات مرّتبہ عبد الباری آسی کی تلاش میں تھاتو انھوں نے مصورِ درد
(عبدالباری آسی مرحوم) کی دل چسپ مولفہ کتاب ”سانس کے عجائبات“ کانام بھی لیا اور کہا ”تمہارے کام کی ہے“۔ ظاہر ہے یہاں ان کی مراد میرا سائنسی پس منظر تھا۔جب یہ کتاب میرے مطالعے سے گزری تو چودہ طبق روشن ہو گئے۔ یونانی طب میں کھانے پانی کے یکساں ذرّاتی سطح (moleculer level) کا اصول اہم ہے، میرے گمان میں ہاشمی صاحب اسی اصول پر کاربند تھے۔
ان کی اندک خوری سے عمر خیام یاد آتا:
گر بادہ خوری تو با خرد منداں خور
یا با صنمی لالہ رخی خنداں خور
بسیار مخورورد مکن فاش مساز
اندک خور و گہ گاہ خور و پنہاں خور
وہ ”کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا“ کا مجسم اور متحرک اصول تھے۔ اوپر میں نے ان کے گھر میں ایک افسر کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ اس مجلس میں جب اس ادب کے پُتلے نے عرض کی، ”استاذ!آپ بھی میرے ساتھ کھائیے“ تو کہنے لگے: نہیں میں اب رات کو کھاؤں گا، صبح دو انڈے اور ایک گلاس دودھ پیا تھا۔ سبحان اللہ! کم خوری ملاحظہ کیجیے: یہ ظہر کا عمل تھا۔
معاملہ یہ ہے کہ ہر ذمہ دار اورعاقبت اندیش انسان کی طرح انھیں احساس تھا: رات تو تھوڑی ہے بہت ہے سوانگ!ظاہر ہے جو شخص بیماری اور طبیعت کی سخت بے چینی میں مقصدِ حیات کو بھلائے نہیں بھولتا، اسے پیٹ کا جہنم کیسے جلا سکتا ہے۔مجھے یاد ہے اورینٹل کالج کی پرانی کینٹین میں ایک مرتبہ ان کے ساتھ چائے کا موقع ملا۔ قسمت سے اس دن ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ مجھے ان کی طبیعت معمول سے زیادہ مضمحل لگی۔ میری تشویش پرجو کلمہ ان کے منہ سے نکلا، وہ اصول ِ حیات بنانے کے قابل ہے:”بیٹا! وہ کام جو ہم کر لیتے ہیں، وہ نہیں تھکاتے، تھکاتے تو وہ ہیں جو ہونے سے رہ جاتے ہیں“۔بعد میں ایسا ہی جملہ جناب خورشید رضوی صاحب کی بابت بھی سننے کو ملا۔
ہاشمی صاحب ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو وقت کی تنگ دامانی کا گلہ کریں، انھیں لمحوں کی وسعت کا اندازہ تھا۔ مشفق خواجہ نے ان کے نام ایک خط میں لکھا ہے:”گوشہ ء خاموشی میں آ پ کا چپکے چپکے کام کرنا آ پ سے اخلاص سے محبت کرنے والوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے“۔میں نے تین چارمقامات پر شبلی اور آرنلڈ کا واقعہ ان کی زبانی سنا۔ معروف ہے: ایک بار بحری سفر میں شبلی اور آرنلڈہم سفر تھے، طوفان آ گیا؛ جہاز ڈوبنے کی ساعت میں آرنلڈ بڑی تسلی سے کتاب پڑھنے میں گم ہو گئے۔ شبلی نے حیرت و خوف کا اظہار کیا تو فرمانے لگے: جب دنیا سے گزرنا ہی ہے۔کیوں نہ علم میں اضافہ کرتے ہوئے گزر جائیں۔ظاہر ہے یہ بہت مشہور قصہ ہے، اکثر اساتذہ اسے بیان کرتے ہیں لیکن عامل کی زبان سے عمل کی بات سننے کا لطف ہی اور ہے۔ خورشید رضوی صاحب کے بہ قول: باکردار شخص عام واقعے میں اخلاص کی وہ چمک پیدا کردیتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ہر بڑے انسان طرح وہ اپنی محنتوں کا اظہار کرتے ہوئے کتراتے تھے۔ شاید یہ سب باتیں مثالی معلوم ہوں، لیکن حق یہی ہے: نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔
دوسروں کی مدد کرنے میں ان کا دل بڑا فراغ تھا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں دورانِ تدریس انھوں نے ایک لائق طالب علم (جو اب مُلک کے معروف سرجن ہیں)کی فیس کا تمام تر ذمہ اٹھا رکھا تھا۔ان کا طلبا کے ساتھ ایسا ربط تھا کہ وہ اپنے مالی مسائل پر ان سے کھل کر بات کرتے۔ وہ ضرورت مند وں کی مدد بھی کرتے اور ذرائع آمدن بڑھانے کے جائزطریقے بھی سجھاتے۔قرض لینے اور قرض دینے کو قطعی برا نہ جانتے البتہ اس کی ادائیگی اور وصولی دونوں میں اصول کا تقاضا کرتے۔ اورینٹل کالج میں ایم فل کے ایک طالب علم(جو میرے دوست ہونے کے علاوہ معروف شاعر بھی ہیں)کو انھوں نے صرف میرے بھروسے پر قرض کی اچھی خاصی رقم تھما دی۔ ان کے اس عمل سے میرے دل میں ان کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ وہ اپنے اعمال سے دوسروں کے اندر اعتماد کی فضا پیدا کرتے۔ ذہین طلبا جماعت سے غیر حاضر ہوتے تو ان کی خیریت دریافت کرتے؛ یہاں تک کہ اورینٹل کالج کے وولنر ہوسٹل تیمار داری کو تشریف لے جاتے۔ انھیں دیکھ کر ہمیشہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے ممدوح یاد آتے؛ جگر سوزی و جاں نثاری سے لبریز، ’کچی بارک‘ کی ٹھنڈی راہ داریوں میں متین اورمستحق طلبا کی دل جوئی کرتے ہوئے، ہائے وہ ان کا پاکیزہ اور بے لوث تبسم، سچ ہے:
ساری ظلمت کا اک قبیلہ ہے
سب چراغ ایک خاندان کے ہیں
طالب علم کوئی سوال کرتا تو اسے فوری جواب دینے کی بجائے خود جواب ڈھونڈنے کی طرف مائل کرتے۔کتاب خانے کی راہ دکھاتے؛ گویا وہ اس انگریزی مقولے کا عملی نمونہ تھے:
Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime
اورینٹل کالج کا کتاب خانہ انھیں حفظ تھا، کون سی الماری کون سی راہداری میں ہے: الماری کی فلاں قطار میں دائیں ہاتھ کو پانچویں کتاب!
کتاب کی ترتیب یاد رکھنے میں مرحوم وحید قریشی کے بعد وہ سب سے زیادہ حسّاس تھے۔طالب علموں کو کتاب خانے بھیجنے کے لیے نئی نئی ترکیبیں سوچتے؛ ان کی لائی ہوئی معلومات کو نہایت غور اور انہماک کے ساتھ سنتے۔
کسی بھی مطلوبہ موضوع پر ان کے پاس کتابوں کے عنوانات کی نہ ختم ہونے والی فہرست ہوتی۔میرے ذاتی کتب خانے میں کئی کتابیں ان کی تحفہ کردہ ہیں۔ مجلس کے شائع کردہ کلیاتِ مصحفی کی چوتھی جلد میرے پاس نہ تھی، ان دنوں میں مصحفی کو پڑھ رہا تھا۔میں نے سرسری اس بات کا ذکر کیا۔ کچھ ہی دن بعد انھوں نے مطلوبہ جلد میرے پتے پر بھیجوا دی۔ ہاشمی صاحب پڑھے لکھے انسان کی دل و جان سے قدر کرتے۔ انھیں میرے نامکمل طبّی سفر کی روداد کا علم تھا، گاہے گاہے مجھ سے مختلف طبی اصطلاحات کی بابت دریافت کرتے رہتے۔ خوردوں سے ایسا سلوک میں نے سوائے استاذی ڈاکٹر مظہر معین حفظہ اللہ کی ذات کے کم لوگوں میں دیکھا ہے۔
ان کا حافظہ آخری دور تک بے مثال رہا۔اس میں یقیناً قرآن پاک کے اعجاز کو بھی دخل ہو گا۔ ان کے حفظ ِ قرآن کا واقعہ بھی عا م صورتوں سے عجیب ہے۔ انھوں نے سن پچاس کی دہائی میں دس برس کی عمر میں قرآن اپنی لوحِ دل پر محفوظ کر لیا۔ عام قاعدہ ہے کہ لوگ حفظ سے پہلے ناظرہ اور قراتِ قرآن کا دَور مکمل کرتے ہیں۔ ان کی کیفیت اس کے برعکس رہی؛ پہلے ہی دن جب انھیں قرآن پڑھنے بٹھایا گیا تو کچھ آیات یاد کرنے کو کہا گیا، مطیع بچے کے طور پر انھوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن کچھ اور مبیّنات؛ وہ بھی حفظ کر لی گئیں اور یوں قرآن کو سینے میں اتارنے کاعملِ کبیر بغیر کسی ظاہری تشہیر کے ہو گیا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ واقعہ جتنا سادہ معلوم ہوتا ہے، ان کے لاشعور پر اس کااثر اتنا ہی وثوق انگیز رہا۔ زندگی بھر تحقیق و تدوین کے میدان میں انھوں نے نادر الوجود کارنامے بغیر کسی تمہیدونمائش کے تکمیل کو پہنچائے۔قرآ ن کا ایک جیبی نسخہ ہر وقت ان کی صدری میں ہوتا، اسے گاہے گاہے پڑھتے رہتے۔ اس بات کا خاص خیال رکھتے کہ لوگوں کے درمیان مذہب کی تشہیر نہ ہو، جتنی خاموشی سے قرآن کی تلاوت کرتے، ویسے ہی سکون سے نماز کر واپس چلے آتے۔
ہاشمی صاحب کو القاب واوصاف سے حقیقی طور پر بیزاری تھی۔ ان کے خاندان کی مذہبی روایت خاصی معروف ہے، اس میں اکابرین ِماضی کے علاوہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، نگت ہاشمی، حکیم عبدالعزیز ہاشمی، حکیم عبدالرحمن ہاشمی شامل ہیں لیکن انھوں نے کبھی از خود اس روایت کا تعارف نہیں کروایا۔ ہمارے ایک نوجوان اور باذوق شاگرد حسنین مظہری پہلی ملاقات میں ان سے ملے تو اپنے ہاشمی ہونے کا تعارف کروایا، انھوں نے کہا: بیٹا ہاشمی ہو کر بھی کیا ہو گا اگر علم وعمل کی خورجین خالی رہی۔! سچ یہ ہے کہ ان کا جعبہ علم وعمل کے موتیو ں سے پُر تھا لیکن وہ دل پایا تھا کہ ہر لحظہ ترقی پر نگاہ تھی۔ ہل من مزید کے سائل کو ہر موجودہ منزل ہیچ معلوم ہوتی ہے۔ان کے مزاج کی فروتنی و بے نفسی مقصود پر نظر رکھنے سے پیدا ہوئی تھی۔
مولوی عبد الحق مرحوم نے لکھا ہے کہ حالی اپنی کتابوں کی تصنیف کے حوالے سے اس حد تک عاجز و بے ریا تھے کہ سرورق پر اپنا نام مولف کے طور پر لکھتے تھے۔ کسی مجلس میں ایک شائق گلے کا ہار ہو گیا، ”مسدس“ کی تعریف و تاثیر کے پُل باندھ دیے۔ حالی کی سادگی و شرافت محاورہ ہے۔ انھوں نے بچاؤ کی راہ یہی دیکھی کہ عبدالحق کی طرف اشارا کیا اور معصومیت سے کہا: یہ اسے نہیں مانتے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص مولوی صاحب مرحوم کے گلے پڑ گیا۔ نیر مسعود کے بہ قول:کسر نفسی یہ نہیں کہ آپ اپنی تعریف کے جواب میں عاجزانہ کلمات ادا کریں،خاکساری کا تقاضا ہے کہ ایسے پہلو بدلیں کہ موضوع ہی کی تقلیب ہو جائے۔ہاشمی صاحب بھی ہو بہواسی حربے سے کام لیتے۔ اپنا ذکر یا کارنامہ سن کر فوراً موضوع بدل ڈالتے۔
گھر میں ملاقات کے حوالے سے وہ سختی سے وقت متعین کر لینے کے اصول پر کار فرما تھے۔ اس کے پیچھے کثرتِ کار کے علاوہ ان کے دائمی ضعف کو بھی دخل تھا جو پوری عمراُن کا رفیق رہا۔ علاقے کے اشتراک سے حاصل ہونے والے اعتماد نے مجھے قدرے بے باک بنا دیا تھا؛ بعض اوقات میں وقت بے وقت بھی حاضر ہوتا، شروع میں تو ”خطائے نخست“ کے مصداق انھوں نے برداشت کیا لیکن ایک دن بڑی رُکھائی سے کہا: آپ وقت لے کر آئیں،میں آرام اور عبادات کے اوقات میں خلل نہیں کرتا۔ بعد میں معلوم ہوا، مسلسل کام کرتے رہنے سے ان کے جوڑ وں میں مستقل درد رہنے لگا تھا۔ قیلولے کے بغیر وہ اپنی جانِ نحیف کو کام پر آمادہ نہ کر پاتے۔یہ قلیولہ بے حدمختصرہوتا۔ وقت گزرنے کا احساس انھیں بے چین رکھتا۔ ایک روز اورینٹل کالج کے شعبہ اقبالیات میں ملاقات کوحاضر ہوا توکہنے لگے:سر میں شدید درد ہے۔چہرہ درد کی کیفیت کا غماز تھا، بار بار پہلو بدلتے تھے۔ ڈاکٹر اکرم اکرام مرحوم نے ڈسپرین کھانے کو دی، اسے کھانے کے بعد سر میز پر ٹکا لیا۔ ابھی پانچ ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ دوبارا سر اٹھایا اوربستے سے پروف کے کاغذنکال کر پڑھنے لگے، ڈاکٹرصاحب نے بہت منع کیا لیکن ہاشمی صاحب نے ”اللہ خیر کرے گا“ کہہ کر اپنا کام جاری رکھا۔
ایک بدیہی صفت جن کو ان کے ہر چاہنے والے نے محسوس کیا ہو گا اُن کے ذہن کا تحلیلی وظیفہ تھا۔ وہ چیزوں کو اس حد تک سادہ اور صاف الفاظ میں بیان کرتے کہ معاملہ آئینہ ہو جاتا۔ پریم چند نے اپنے ایک افسانے میں لکھا ہے: فربہی بہ جائے خود رعب کا باعث ہے۔ ہاشمی صاحب کی جسمانی نقاہت اور آہستگیء صوت نے ایسی صورت پیدا کر دی تھی کہ اکثر لوگ انھیں فلسفیانہ اعتبار سے بڑا سیدھا جانتے تھے، ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ:
لوگ دب جائیں گے لہجے کی توانائی سے
اس طرح بول کہ آواز سے ڈر لگنے لگے
ان کے منہ سے نکلے ہوئے سادہ جملے میں نے جب بڑے ادیبوں کی کتابو ں میں پڑھے تو مجھے ان کے مطالعے کی وسعت اور مشاہدے کی قوت کا احساس ہوا۔ایک بار انھیں نے راہ چلتے کہا:دیکھیے ان لوگوں سے بچ کر رہیں جن کے ہاتھ میں آپ نے کبھی کتاب نہیں دیکھی۔میں اس جملے سے بہت چونکا۔ بہت بعد میں معروف امریکی ادیب مارک ٹوین کو پڑھتے ہوئے میں نے ایسا ہی جملہ پڑھا تو میں بہت متاثر ہوا۔ میر تقی میر سے میرا اشتغال بہت سامنے کا ہے، ایم اے کے زمانے میں میر کا کوئی نہ کوئی دیوان ہاتھ میں ضروررہتا۔ ایک مرتبہ استادم اشرف آصف صاحب منصورہ تشریف لائے، میں ان سے ملنے گیا، واپسی پر ہاشمی صاحب کے گھر بھی گیا۔میر کا دیوان دیکھ کر خوش ہوئے، باتوں باتوں میں کلاسیکی شاعروں کا ذکر ہوا تو کہنے لگے: ہمارے ہاں تو وہی کلاسیک ہے جس کا نام معروف ہو جائے چاہے لوگ اسے پڑھیں یا نہیں۔ بعد میں کھلا کہ یہ انگریزی کا معروف مقولہ ہے:
Classic: A book people praise and do not read.
شاید یہی وجہ ہے کہ کلاسیکی ادب کے بڑے پارکھ اور لغت نویس رشید حسن خاں انھیں ”پیر جی“ کہتے۔ رشید حسن خاں سے ان کی خط و کتابت کی یہاں تک شہرت تھی کہ خاں صاحب کے انتقال کے بعد اکثر لوگ ہاشمی صاحب سے پوچھتے: کلاسیکی ادب کی فرہنگ کی جلد دوم کیا آپ کی ملکیت میں ہے؟اس جلد کی بابت تو معلوم نہیں ہو سکا البتہ وہ جدید املا اور اس کے اصولوں میں قریب قریب رشید حسن خاں کی مکمل پیروی کرتے تھے؛ لفظوں کو توڑکر لکھنا،حمزہ اور یے کے مسائل، امالہ کی صورتیں؛ ان سب معاملات میں وہ انھی کی رائے کو صائب جانتے۔
رشیدحسن خاں اور نیر مسعود میں گہری دوستی تھی، آخری زمانے میں لکھنو کی تہذیب اور نوابوں کے تمدن پر زبردست اختلافات بھی ہوئے۔ نیر مسعود پر اپنی پی ایچ ڈی کے زمانے میں مجھے ہاشمی صاحب سے بعض ایسی معلومات ملیں جو اور کسی طرح حاشیہ خیال میں نہ آ سکتیں۔
میں نے کبھی نہ سوچا تھاکہ مرثیہ بھی ان کا میدان ہو سکتا ہے لیکن گورنمنٹ کالج لاہور کے کتاب خانے کے دستاویزی سیکشن میں انھوں نے مرثیے کے چند نادر اور کم دیدہ ماخذ کی نشان دہی کی۔ اسی دستاویزی سیکشن میں ایک مخطوطے کا ذکر کیا؛ جس میں ہاتھ سے پختہ سیاہی کے ساتھ کلام ِ انیس کے جنگی آلات کی تصویریں بنائی گئی تھیں، بعد ازاں اس مخطوطے کی یافت اور تفہیم ان کا ایسا احسان ہے جس کا نقش دل پر مرتسم ہے۔ افسوس کہ یہ مخطوطہ ناقص الاول و آخر ہے۔
کم گوئی نے انھیں چیزوں کے اظہار سے بے نیاز بنا دیا تھا۔ان کا اصول یہ تھا:جتنا جانتے ہو اس سے کم بولو۔ ہمارے ہاں علمی حلقوں میں ا س کے برعکس صورت ِ حال پیدا ہوگئی ہے۔جذبات پر قابو رکھنے کے اس سخت مجاہدے نے انھیں مضبوط بنا دیا تھا۔ وہ احمد مشتاق کے شعر کا چلتا پھرتا ثبوت تھے:
اس لیے حالِ دل نہیں کہتا
کہیں جذبات میں نہ بہ جاؤں
میں نے روزمرہ زندگی کے معاملات کو ان پر کم اثر انداز ہوتے دیکھاہے۔ جوان بیٹے کا کھونا چھوٹا صدمہ نہیں، ایسے موقع پر پامردی دکھانا اور امنّا و صدقنا کہنا حقیقی مردانگی ہے۔اپنے چودہ سالہ تعلق کے دور ان میں نے ان کے چہرے پر کبھی گلہ مندی کا چھینٹا نہ پایا۔وہ ان لوگوں میں سے تھے جو جینے کے جواز خود پیدا کرتے ہیں۔ بہت بچپن میں ماں او ر اکلوتی بہن کو کھو دینے سے جو رخنہ ان کے ذہن میں پیدا ہوا، اسے ان کی ا عصابی مضبوطی نے پُر کیا۔ ان کی شخصی مزاولت اور غیر متزلزل صفات کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ وہ بڑے آدمیوں اور حقیقی رشتوں کے جویا تھا۔ مختار مسعو دکے قول:بڑے آدمی زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں، کے مصداق وہ اسی مثالی دنیا کی سیرو سیاحت میں گم رہتے۔
سیر و سیاحت سے یاد آیا: مناظر فطرت سے ان کی رغبت مجھے مرحوم مظہر محمود شیرانی کی یاد دلاتی۔ ڈاکٹر صاحب کے معاصرین جانتے ہیں کہ فطرت کا ذکر ہی ان کے چہرے پر مترشح کے رنگ پیدا کر دیتا۔ سیر وفی الارض کو حکم جانتے ہوئے انھیں دنیا گھومنے کا بھی موقع خوب ملا۔ انھوں نے زمانے کی قید سے آزاد، آنے والی روحوں کو بھی اپنے احساس ِ فرحت میں شریک کر لیا اور دو سادہ لیکن دل پذیر سفر نامے تحریر کیے۔حال ہی میں شائع ہونے والے ان کے سفر نامے ”۔۔۔لوگ جہاں میں۔۔۔اچھے“کے پیش گفتار میں ان کی جوانی کے دوست و ہم کار اور معتبر مورخ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے سفر ”فرصت کے لمحات میں ان کی چشمِ باطنی پرجلوہ افروز رہتے ہیں۔“اس حساب سے انھیں اختر شیرانی کی فطرت پسندانہ نظموں کے بند کے بند یاد تھے، جسے مزاج کی بشاشت میں دہراتے رہتے۔
ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے لاہور سے چکوال کا فاصلہ کافی زیادہ تھا لیکن جب استادِمحترم پروفیسر سعید اکرم حج کے فریضے سے واپس آئے تو
اپنی صحت کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنی اہلیہ کے ہم راہ چکوال کے معروف نواحی گاؤں سہگل آباد تشریف لائے اور ان کو سفر نامہ لکھنے کی ترغیب دی۔ جب یہ سفر نامہ چھپ کر آیا توبہت خوش ہوئے۔ ہاشمی صاحب ذہین لوگوں کے کام سے برابر خوش ہوتے؛ اس صفت نے ان کے سینے میں برکت کی وسعت پیدا کر دی تھی۔
ہاشمی صاحب کو دیکھ کر ان کے ظریف ہونے کا کم ہی احساس ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا مزاح تہذیب کے آبِ صفا سے دُھلا ہوتا؛اس میں قوسِ قزح کے رنگوں ایسی نظافت موجود ہوتی۔ میں نے انھیں آج تک قہقہہ لگاتے نہیں دیکھا، لیکن چہرہ ہمیشہ متبسم رہتا۔وہ تہذیبی مزاح کے لیے اکثر ”مزاحِ ملیح“ کے الفاظ استعمال کرتے،افسوس کہ اب لوگ مزاح میں سنجیدگی کے تناسب اور سنجیدگی میں مزاح کے حساب سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ طلبا کے ساتھ ان کا مشفقانہ رویہ لطافتِ اسلوب کا اظہار ہوتا۔ ہمارے ایک دوست نے انھیں اپنے شیخوپورہ سے تعلق کا بتایا تو ہنس کر کہنے لگے: آپ کا لہجہ خود اس تعلق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ہمارے دوست شیخوپورہ کو اپنے خاص دیسی انداز میں شیخپرہ کے تلفظ میں ادا کررہے تھے۔
مرحوم اپنے ذوق کی چیزوں کے لیے بعض اوقات روزمرہ ضروریات تک سے بے گانہ ہو جاتے۔ مجھے یاد ہے، ایک دن شعبہ اقبالیات میں معمول کی گپ شپ اور چائے نوشی کے بعد میں گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی آ گیا۔ گھنٹہ نہ گزرا ہو گا کہ مجھے ان کی کال آئی، میں ا س وقت کلاس پڑھا رہا تھا۔ کہنے لگے:”اورینٹل کالج کے باہر فٹ پاتھ پر میری نظر ایک کتاب پر پڑی ہے، ”اقبال بچوں کے لیے“ پرانی جلد کی معلوم ہو رہی تھی،رنگ زرد تھا۔ افسوس! میں نے اسے گزرتی ہوئی گاڑی سے دیکھا ہے، جب سے گھر آیاہوں، ذاتی کتاب خانہ کھنگال ڈالا ہے لیکن ایسی کوئی کتاب میرے پاس موجود نہیں، خدا را آپ فورا ً ابھی چلے جائیں، ایسا نہ ہو کتاب کوئی خریدلے۔ میں نے انھیں یقین دلانے کے بعد فون بند کر دیا۔ کلاس ختم ہونے میں پندرہ منٹ تھے، اس دوران ان کی تین کالیں آئیں، آواز سے اضطراب واضح تھا، بالآخر کتاب خرید کر انھیں خبر کر دی گئی، اس کے بعد انھیں سکون ہوا۔ اپنے پسند کی کتاب کے لیے بے چین ہو جانا شاید کوئی غیر معمولی بات نہ ہو، لیکن ان کی سِن رسیدگی کو دیکھتے ہوئے یہ واقعہ قابلِ لحاظ ہے۔ ساڑھے سترہ سو صفحات سے متجاوز ’’کتابیات ِ اقبال“ جیسا قاموسی کارنامہ ایسے ہی مجنونانہ شوق کا حاصل ہے۔ اس کتاب کی تالیف کی داستان لکھی جائے تو رندانہ ذوق کی ایسی درجنوں مثالیں سامنے آ سکتی ہیں۔
وہلیبن نے کہیں لکھا ہے: بڑھا پا کسی ناگہانی آفت کی طرح اچانک نازل ہونے والی افتاد ہے، سلسلہ نہیں۔ عام دنوں میں شاید آپ اس فطرت پرست کی داد دیں، لیکن ہاشمی صاحب کو دیکھ کر وہلیبن کی حکمت مشکوک ہو جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کے بارے میں گمان نہیں ہوتا کہ ان پر جوانی گزری ہو گی، ہاشمی صاحب ان ہی میں سے تھے۔ میں نے ظاہر ہے، ان کی جوانی نہیں دیکھی لیکن ثقہ راویوں نے میرے موقف کی
تصدیق کی ہے۔ میں نے اَسّی کی دہائی کے ان کے فوٹو بھیدیکھے ہیں،وہی نزاری، وہی احتیاط پسندی۔ ہاں بالوں میں چاندی کے تار البتہ خال خال تھے۔ہاشمی صاحب کو دیکھ کر ٹالسٹائی کی کردار ویرونیکا کی یاد تازہ ہو جاتی تھی جس کے بارے میں اس نے لکھا کہ و ہ انیس برس کی بھی ہو سکتی ہے اور تیس کی بھی اور اس سے قطعی فرق نہیں پڑتا۔
اقبالیات میں مستغرق ہونے کے باوجود وہ مروجہ اور مستند ادب سے بیگانہ نہیں ہوئے تھے۔۷۱/۶۱۰۲ ء میں جب وہ شعبہ اقبالیات میں تشریف لاتے تو میں ان کی زیارت کو جاتا۔ ان دنوں وہ اپنے صبح و مسا کے رفیق نما شاگرد قاسم محمود احمد صاحب کے ہم راہ ہوتے۔ وہاں ان سے متنوع موضوعات پر بحث ہوتی۔ ایک روز مثنوی کے دفتر ِ ششم پر بحث ہوئی، میں نے انھیں دو چار شعر انھیں سنائے، ان کا انہماک ملاحظہ کیجیے کہ انھوں نے تین بار وہ شعر مجھ سے سنے۔ پھر ابوالخیر سعید کی رباعی اور منطق الطیر کے کچھ اشعار بھی سنائے۔منطق الطیر پر بات ہوئی تو تکملے کے طور پر سنائی غزنوی بھی زیرِ بحث آئے۔میں ان دنوں ھدیقہ سنائی کا انگریزی ترجمہ” “The Enclosed Garden of thr Truth پڑھ رہا تھا۔ انھوں نے ھدیقہ کے متعلق اتنی معلومات بہم پہنچائیں کہ مجھے یہی موضوع ان کا اختصاص معلوم ہونے لگا۔یہی حال عربی ادبیات سے واقفیت کا بھی تھا؛ گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی کے ایک پروگرام کے آخر میں ان سے گفت گو ہو رہی تھی۔میرے منفرد شوق کو دیکھتے ہوئے وہ زیرِ مطالعہ کتب کا ضرور پوچھتے۔ میں نے البیرونی کی ”کتاب الجواھر“ (اردو ترجمہ،کتاب الجماھر فی معرفتہ الجواھر)کا ذکر کیا۔ انھیں اس موضوع سے ایسی دل چسپی ہوئی کہ کھانے کو چھوڑ کر وہ البیرونی پر گفت گو فرماتے رہے۔ میں خجالت سے بار بار ان کی توجہ طعام کی طرف کرتا، لیکن گویا انھیں اپنی پسند کا موضوع مل گیا تھا۔ انھیں ڈاکٹر عطش درانی کے ترجمے کے بارے میں یہاں تک علم تھا کہ ترجمہ کرتے ہوئے انھوں نے کون کون سا حصہ عمداً چھوڑ دیا تھا۔
اقبال کے “The Reconstruction of Religious Thought in Islam” کے درجنوں اردو تراجم اور اصل انگریزی متن سے بھی ان کی واقفیت حیران کن تھی۔مجھے ان ہی کی زبانی ایک دل چسپ واقعے کا علم ہوا۔ جن دنوں شہزاد احمد مرحوم خطبات ِ اقبال کا اردو ترجمہ کر رہے تھے؛ وہ اپنا ترجمہ اشفاق احمد کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بھیجتے۔ غالباً دوسرے خطبے کے کسی انگریزی اقتباس کی بابت شہزاد احمد نے پوچھا کہ اس حصے کا مناسب اور قابلِ فہم اردو ترجمہ کیا ہو سکتا ہے۔ اشفاق احمد نے کہا: چوں کہ یہ حصہ نہایت دقیق اور دور از کار ہے، مناسب ہے اسے ترجمے سے حذف کر دیا جائے۔ یہ قصہ سنانے کے بعد ہاشمی صاحب زیرِ لب اپنے مخصوص انداز میں مسکرانے لگے۔ عربی فارسی، اردو انگریزی کی مستطیل سے انھوں نے بہ یک وقت موجودہ زمانے اور قدیم دنیا سے اپنا تعلق برقرار رکھا تھا۔
ان زبانوں نے ان کے اندر وہ تہذیبی رچاؤ پیدا کیا تھا جس کی مثال اب مشکل ہی سے ملے گی۔
مذہب ابو الکلام آزاد کے بہ قول: ان کے لیے ایسی دیوار تھی جس نے ہر حال اور ہر وقت میں انھیں سہارا دیے رکھا۔ جدید تعلیم کے مضمرات سے کون واقف نہیں، خود سر سید مرحوم آخری برسوں میں اس شترِ بے مہار سے نالاں تھے۔ ہاشمی صاحب نے دنیاوی و ادبی مناسبات میں دین کو ہر حال میں انسب جانا؛ سچ تو یہ ہے کہ وہ کلام ِ اقبال کے شارح ہونے کی بجائے اس کے عامل تھے:
دیں ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی
فطرت ہے جوانوں کی زمیں گیر زمیں تاز
مذہب نے ان کے اندر سختی پیدا کرنے کی بجائے پختگی کو جنم دیا تھا۔ وہ اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کا احترام کرنا جانتے تھے۔ میں بہت سے ایسے موقعوں کا چشم دید گواہ ہوں، جب ان کا مخاطب متضاد خیالات کا حامل ہوتا لیکن ان کی نرم خوئی، ملائمت اور اخلاص مخالف کے دل کو بھی پانی کر دیتا۔
زندگی کے آخری چند برسوں میں جدید فون کا استعمال کرنے لگے تھے۔ آخری کچھ مہینوں میں انھوں نے فلسطین کے لیے ایسی ہم دردی اور جاں گدازی کے پیغامات پہنچائے تھے کہ دل خون ہوتا تھا۔ میں نے اکثر لوگوں کو ان کی مردم بیزاری کا شاکی پایا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میرے ساتھ ان کی فون پر طویل گفت گوئیں ہوتیں۔ بعض اوقات وہ خود کال کرتے اور گفت گو فرماتے۔ اپنی آخری کال میں انھیں اکبر کے کسی مصرعے کی تلاش تھی، میں نے دو چار منٹوں کے تفحص کے بعد استادم خواجہ محمد زکریا کے مرتّبہ کلیات سے شعر ڈھونڈ نکالا تو بہت خوش ہوئے۔
ان کی وفات کی جاں کاہ خبر مجھے دوستوں کی محفل میں ملی۔ نبض ڈوبتی معلوم ہوئی؛ دل بیٹھ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون!
نیاز مند زندگی بے نیاز موت، دفعتاً سودا کا شعر یاد آیا:
ہستی سے عدم تک نفسِ چند کی ہے راہ
دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا
ہاشمی صاحب کی پہلی نمازِ جنازہ مشہور محدث مولانا عبد المالک نے پڑھائی۔ منصورہ کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ہزاروں کے مجمعے نے ا س مہ ِ کامل کے غروب کا دیدار کیا۔سیکڑوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔جامعہ پنجاب میں ان کی نمازِ جنازہ ان کے محبوب شاگرد محترم استاد پروفیسر زاہد منیر عامر صاحب نے پڑھائی۔ کیسا عجیب اتفاق ہے، چار دہائیوں قبل ہاشمی صاحب ہی کی تشویق پر زاہد صاحب ایم اے کے طالب علم کے طورپر اورینٹل کالج تشریف لائے؛یہ خوش اختلاطی یوں انجام کو پہنچی۔ تقدیر شاید اسی دن کے انتظار میں تھی۔ تدفین جامعہ پنجاب ہی کے قبرستان میں ہوئی:
خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ
ہم نے سونا سپردِ خاک کیا