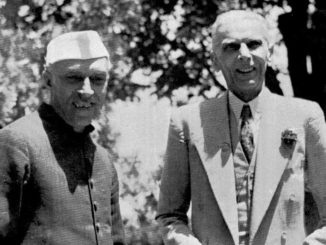ثقافت کی لُوٹی ہوئی جاگیر
از، خضرحیات
میں اپنی اوّلین یادوں کو ذہن کے پردے پر جگاؤں تو ایک یاد ایسی ہے جس نے مجھے بچپن میں سب سے زیادہ مسحور کیا تھا۔ میرے ابّا نے جس دن مجھے یہ بتایا کہ پاس کے گاؤں میں ایک بزرگ کے سالانہ عرس کے دوران مقامی تھیئٹر میں وہ لوک داستان ہیر رانجھا کو ڈرامائی صورت میں دیکھ کر آئے ہیں تو یوں سمجھیں کہ میری آنکھیں حیرت، تجسّس اور خوشی سے کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں۔ میری پیدائش پچھلی صدی کے چھیاسیویں سال کی ہے اور جن دنوں مجھے اباجی نے اس تھیئٹر کمپنی کے بارے میں پہلی دفعہ بتایا تھا اس وقت میں کوئی سات یا آٹھ سال کا بچہ تھا۔ یہ عمر ہر لمحہ ایک تازہ حیرت سے روبرو ہونے اور پھر ان حیرتوں کو سمیٹنے کی ہوتی ہے۔ اس عمر میں بچے بہت زیادہ متجسّس ہوتے ہیں اور شعور کی کھڑکی جو اب آہستہ آہستہ ان پر کھل رہی ہوتی ہے اس میں سے آنے والے بیرونی دنیا کے لطیف جھونکے جہاں حیران کرتے رہتے ہیں وہیں نہال بھی کرتے ہیں۔ یہی وہ دن ہوتے ہیں کہ جب بیرونی دنیا اپنی مٹھی میں قید بے پناہ حیرتوں کے خزانے میں سے کچھ موتی، سکے، گھنگھرو، سیپیاں، بنٹے، رنگ، لکیریں اور کچھ کلیاں آپ کے شعور کی جھولی میں ڈالنا شروع کرتی ہے اور جھولی میں گرتی ہر نئی شے ایک نئی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اپنے تجسّس اور حیرت کی تشفی کے لیے ہی بچے طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں اور ذہن میں پیدا ہونے والی خالی جگہوں کو اتنی ہی دیر میں پُر کر لینا چاہتے ہیں جتنی دیر میں ہتھیلی پر سرسوں جمائی جاتی ہے۔
اس تناظر میں سمجھا جائے تو میرے لیے ابّا جی کی تھیئٹر والی بات بھی اسی لیے بے پناہ حیرت انگیز تھی۔ اُس زمانے میں اگرچہ ٹیلی ویژن بہت زیادہ نایاب تو نہیں تھے مگر کسی قدر کم یاب ضرور تھے۔ میرے دیہات میں تو اس وقت تک بجلی بھی نہیں آئی تھی اور ہمارے بچپن کی راتیں ٹین کی چادر سے بنے اور مٹی کے تیل سے چلنے والے ایک دیئے کی لَو میں ہی نیم روشن ہوتی تھیں۔ گھر میں ٹیلی ویژن نہیں تھا مگر ماموں کے یہاں موجود تھا جو بلیک اینڈ وائٹ تھا اور بیٹری سے چلتا تھا۔ اس بیٹری کو ہر ہفتے سائیکل پر رکھ کر دو گاؤں چھوڑ کر تیسرے گاؤں جا کر اس میں تیزاب تبدیل کرانا پڑتا تھا۔ اب ٹی وی موجود تو تھا مگر اسے بہت زیادہ دیکھنے کی اجازت بچوں کو نہیں ہوتی تھی۔ پھر بھی تھوڑا بہت جتنا میں نے دیکھا مجھے یہ تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ اس ڈبے میں ڈرامے چلتے ہیں، گانے بھی، خبریں بھی اور کارٹون بھی۔ مگر یہ ابھی تک مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ پہلے کسی جگہ پر ریکارڈ ہوتا ہے اور پھر ٹی وی پر آتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق یہ سب کچھ ٹی وی کے اندر ہی ہو رہا ہوتا ہے اور میرا یہی خیال ابا کی جانب سے ملنے والی خبر پر مجھے حیرت میں ڈال گیا۔ میں نے اپنی کشمکش اباجی کے سامنے رکھی تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جس طرح ٹی وی پر ڈرامہ چلتا ہے اسی طرح اسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں اور جیتے جاگتے ہمارے تمہارے جیسے لوگ ہی یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا تجسّس تو کسی قدر کم ہو گیا مگر اس کی جگہ میرے بھرپور اشتیاق نے لے لی۔ میں نے تُرنت ان سے فرمائش کردی کہ مجھے بھی ڈرامہ دیکھنا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلے سال نواحی گاؤں چک سلطانیوالا میں جب حضرت شاہ شمسؒ کا عرس منایا جائے گا تو دونوں ساتھ چلیں گے۔
بچے کی یہ نفسیات ہے کہ اسے یہ نا بھی پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ پکا ہے یا جھوٹ موٹ کا، وہ ہر وعدے کو سچا سمجھ کے اس انتظار میں گھڑیاں گننا شروع کر دیتا ہے کہ کب وہ وقت آئے اور کب وہ اس وعدے کی تکمیل کا دن دیکھے۔ میرے ساتھ ہونے والا وعدہ اگرچہ میرے ابّا کا پکا وعدہ تھا لیکن اگر وہ پکا نہ بھی ہوتا تو بھی میں اسی طرح اگلے سال کا انتظار کرتا رہتا جس طرح میں نے کیا تھا۔ میں دن گننے لگا اور پھر چونکہ سکول کے ابتدائی دن تھے اور میں پرائمری سکول میں روزانہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والی حیرتوں کے ساتھ نبردآزما ہو رہا تھا تو کچھ ہی دنوں میں مجھے یہ بات اس شدت سے یاد نہ رہی جس سے شروع میں یاد رہتی تھی۔ چنانچہ جب سال گزر گیا تو میلہ بھی قریب آ گیا۔ اباّ جی کو اپنا وعدہ یاد تھا اور ایک دن انہوں نے مجھے شام کو تیار رہنے کا کہا اور کام پر چلے گئے۔ شام کو اباّ کام سے واپس آئے تو کسی قدر افسردہ تھے مگر اس عمر میں اور اس دن میرے لیے ان کی افسردگی سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ہم نے آج میلے میں جانا ہے چنانچہ میں نے انہیں گھر میں داخل ہوتے ہی میلے پر جانے والی بات کہی۔ انہوں نے قدرے رُکھائی سے جواب دیا کہ اس سال ہم میلے میں نہیں جائیں گے۔ میری شکل اتر گئی، امیدیں اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتی نظر آ رہی تھیں اور بظاہر کوئی خاص وجہ بھی نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے اس ساعت میں اپنے آئیڈیل ابّو ہیرو کی بجائے یک دم ولن کے روپ میں نظر آنے لگے اور مجھے لگا جیسے وہ عینک والے جن کے سامری جادوگر بن گئے ہیں۔ مجھے ان کا یہ جواب ہضم نہیں ہو رہا تھا تو میں نے بھی قدرے درشتی سے کہا کہ نہیں مجھے میلے میں جانا ہے اور پھر پچھلے سال سے لے کر آج صبح تک ہمارے بیچ زندہ رہنے والے اس وعدے کی یاد دہانی کرائی مگر وہ نہیں مانے۔ میں نے اس دوران محسوس کیا کہ وہ غصے کی بجائے دکھی ہو رہے ہیں۔ میں چونکہ بچہ تھا اس لیے بچوں کی طرح ہی بار بار ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا، ایسا منظر تھا کہ گراموفون ریکارڈ پہ جو فیتا رکھا گیا ہے اس کی سوئی ایک خاص جگہ ‘میلے میں جانا ہے’ پر آ کر اٹک گئی ہے اور بار بار یہی الفاظ نکل رہے ہیں۔ اس دوران میں ادھر ادھر سے سفارشیں بھی کروا رہا تھا۔ اماں سے تو کیا سفارش کروانا تھی، مجھے معلوم تھا کہ اگر انہوں نے غلطی سے بھی سفارش کر دی پھر تو ابّا کسی صورت بھی مجھے نہیں لے جائیں گے۔ لہٰذا اماں کی بجائے میں نے دادا جان سے سفارش کروائی۔ دادا جان کے کہنے پر ابو نے زبان کھولی اور بتایا کہ اس دفعہ میلہ تو لگا ہے مگر تھیئٹر والے نہیں آئے اس لیے ہم نہیں جا رہے۔ ہوا یوں کہ پہلے ایسے میلوں پر ایک سے زیادہ تھیئٹر کمپنیاں آتی تھیں مگر جنرل ضیاء الحق کے دور کی لمبی مار صرف چند ایک کمپنیاں ہی سہہ سکیں اور ہمارے میلے میں آنے والی کمپنی بھی انہی چند ایک کمپنیوں میں سے تھی جس کا تعلق تو ملتان سے تھا مگر اس میں قریبی گاؤں کے لوگ بھی اداکاری کرتے تھے۔ معاشی بدحالی نے اس سال اس ایک آدھ کمپنی کو بھی اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ میلے میں آ کر ایک معصوم بچے کا خواب پورا کر سکتی لہٰذا اس سال تھیئٹر کی کمی نے میلے کی رنگینیوں کو پھیکا کر دیا۔ ٹھیک ایک سال پہلے تھیئٹر والی بات سن کر میرا دل خوشی سے جس قدر اچھلا تھا آج دگنی شدت سے دبک کر ایک کونے میں افسردہ سا بیٹھ گیا تھا۔ زندگی کبھی چونکائے بغیر نہیں رہ سکتی، اسے ہر دم کوئی نہ کوئی تماشہ چاہیے ہوتا ہے۔
اس روز اباجان نے مجھے بتایا کہ میلے ٹھیلے، کھیل تماشے ہماری ثقافت کی صورت گری کرتے ہیں۔ یہی ہماری ثقافت کا چہرہ ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں کی تفریح کا وافر سامان موجود ہوتا ہے اور پھر لوگ ایک دوسرے سے گھل مل بھی جاتے ہیں۔ آس پڑوس کے دیہاتوں سے آنے والے اپنی اپنی فصلوں کے حال سناتے ہیں، مل کے حقہ پیتے ہیں، گیت سنتے ہیں، کبڈی دیکھتے ہیں، موت دے کھوہ میں چلتی موٹر سائیکل دیکھتے ہیں، بازی گر جب اپنے منہ سے آگ نکالتا ہے تو وہ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں، نیزہ بازی ہوتی ہے، سرکس میں تماشے ہوتے ہیں، ورائٹی شو ہوتے ہیں جن میں عورتیں خوش رنگ لباس پہنے اور چہروں پر میک اپ ملے ساری رات میڈم نورجہاں کے گانوں پر رقص کرتی ہیں، لوگ جلیبی کھاتے ہیں، خواتین اور بچے جھولے لیتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، نقل کرنے والے آتے ہیں، بھانڈ اپنی محفل لگاتے ہیں، مقامی مزاحیہ فنکار اپنے مخصوص انداز میں لطیفے سناتے ہیں، مقامی گویّے بلائے جاتے ہیں جن میں اللہ دتہ لونے والا، طالب حسین درد، منصور علی ملنگی، ارشاد ٹیڈی اور بعض بعض جگہوں پر نصرت فتح علی خان کو بھی بلایا جاتا ہے۔ لوگ ملتے ملاتے ہیں اور تین دن میں تازہ دم ہوکر پھر پورا سال ہل، پنجالی اور زمینوں کی سنگت کے لیے پھر سے تیار ہو جاتے ہیں۔ میڈم نورجہاں کے میلے میں سنے ہوئے گیت وہ اپنے بیلوں کو سناتے سناتے سال پورا کرتے ہیں اور پھر سے میلے کے دن آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری ثقافت کا لازمی حصہ ہیں۔ انہی میلوں میں مقامی تھیئٹر کمپنیاں لوک داستانوں کو عام عوام کے لیے اسٹیج پر پیش کرتی تھیں۔ ہیررانجھا، سسی پنوں، سوہنی مہینوال کی داستانوں کو گھر گھر پہنچانے میں انہی کمپنیوں کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب ان لوک داستانوں کے انسانی اخلاق پر پڑنے والے اثرات کا ازسرنو جائزہ نہیں لیا گیا تھا اور نہ ان کے مرکزی کرداروں کے کردار کی نئی تشریح پیش کی گئی تھی۔ یہ جنرل ضیاء الحق کی آمریت سے پہلے کے دور کے قصّے ہیں۔
اباّ جی بتاتے تھے کہ ان میلوں میں ایک سے زیادہ کمپنیاں آتی تھیں اور آج کے دور کے برعکس ایسا نہیں تھا کہ تمام کمپنیوں کا تعلق یا لاہور سے ہو سکتا تھا یا کراچی سے یا پھر اسلام آباد سے۔ ملتان، فیصل آباد، جھنگ، ساہیوال اور دیگر ان سے چھوٹے شہروں میں یہ کمپنیاں بنتی تھیں اور پھر شہر در شہر، گاؤں در گاؤں جا کر کھیل پیش کرتی تھیں۔ مرزا اطہربیگ کے ناول ‘حسن کی صورت حال’ میں ایسی ہی ایک کمپنی ‘لکی سٹار کمپنی’ کے بارے میں تفصیلات درج ہیں۔ ہمارے قریبی گاؤں میں آنے والی آخری کمپنی کا تعلق ملتان سے تھا اور اس میں کچھ مقامی اداکار بھی تھے جو اسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے جہاں میلہ لگتا تھا۔ ایسے ایک فنکار کا نام مجھے یاد ہے ‘استاد گامن جھتّہ’ اور مجھے پچھلے دنوں اطلاع ملی تھی کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ زندگی اگر مجھے اور انہیں مہلت دے تو میں کسی روز ضرور ان سے ملنا چاہوں گا۔ انہی مقامی فنکاروں کا اثرورسوخ تھا کہ ہر سال یہاں تھیئٹر کمپنی ضرور آتی تھی۔ ابا جی بتاتے تھے کہ استاد گامن ان لوک داستانوں کی اسٹیج پر پیشکش کے دوران ہیر، سوہنی اور سسّی کا کردار ادا کرتے تھے اور اتنا جچتے تھے کہ لوگوں کے ذہن میں وہ ہیر، سوہنی اور سسّی کی مجسم شکلوں کی صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے تھے۔
یہ تھیئٹر کمپنیاں اس حساب سے میلوں کا انتخاب کرتی تھیں کہ انہیں آرام کا بھی وقت مل سکے اور ریہرسل کا بھی۔ تھیئٹر میں ان کی پرفارمنس دیکھ کے یقین ہو جاتا تھا کہ یہ لوگ سارا سارا سال ریہرسل بھی جاری رکھتے ہیں۔ اتنی ریہرسل کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پانچ سے آٹھ گھنٹے (جی ہاں میں نے صحیح لکھا ہے) کے ڈرامے کا سکرپٹ زبانی یاد رکھا جا سکے۔ ہوتا یہ تھا کہ رات کو بارہ بجے ایک کھلے میدان میں تنبُو لگا کر یہ کھیل شروع ہو جاتا۔ فنکار اپنے اپنے ایکٹ کے مطابق اسٹیج پر آتے رہتے اور اپنے مکالمے ادا کرتے رہتے۔ زیادہ تر فنکار مرد ہی ہوتے تھے اس لیے یہ لازمی تھا کہ وہ ایکٹ کے مطابق میک اپ کرتے اور اسی حساب سے کاسٹیوم بھی پہنتے۔ لوک داستانیں ویسے بھی مقامی لوگوں کے دلوں کے بہت قریب ہوتی ہیں اور کسی کو ہیر کے رانجھے کے ساتھ بھاگ جانے پر اعتراض نہیں ہوتا بلکہ ہیر کے رانجھے کے ساتھ بھاگنے کو وہ سچی محبت کی جیت سمجھ کر خوش ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کیدو جو بظاہر ہیر کو شادی سے پہلے ‘ناجائز’ تعلقات قائم کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے وہ ہمارے پنجابی سماج میں ولن کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یہی وہ پیار، محبت اور برداشت کا کلچر تھا جو اُس وقت کے سماج میں موجود تھا اور میرے بچپن کے دنوں تک یہ بہت حد تک برقرار رہا۔ اُن وقتوں میں میلہ دیکھتے ہوئے شاید کسی دیہاتی کے بھی ذہن میں یہ خیال نہیں ابھرا ہوگا کہ مستقبل قریب میں ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے جب کیدو کو ہیرو اور رانجھے کو ولن بنا دیا جائے گا۔ اباّ جی بتاتے تھے کہ اس وقت ایک شو کی ٹکٹ پانچ روپے ہوتی تھی جو کہ اس دور کے حساب سے اچھی خاصی رقم تھی مگر ہر دیہاتی یہ شو دیکھنا فرض سمجھتا تھا۔ تنبو لگا کر کھیل اس لیے شروع کیا جاتا تھا کہ کوئی ٹکٹ کے بغیر نہ گھُس آئے لیکن جونہی رات ٹھنڈی ہو کر سکون کی آغوش میں چلی جاتی اور سب لوگ کھیل میں ‘کھُب’ جاتے تو تنبو کھول دیئے جاتے اور کھلے میدان میں تاروں بھرے آسمان کے نیچے سچے پیار کے کھرے بولوں کو ہوا اپنے پروں پر بٹھا کر دور دور تک چھوڑ آتی تھی۔ فضا پر محبت کے گیتوں کی حکمرانی قائم ہو جاتی تھی۔
پہلی بات جو لوگوں کو تھیئٹر میں کھینچتی تھی وہ تو بذات خود کہانی ہی تھی۔ محبت کی کہانی سننا سبھی کو ہی اچھا لگتا ہے۔ دوسری اہم بات تھی اس کہانی کی پیشکش اور فنکاروں کی مہارت۔ سال بھر کی ریہرسل کے بعد وہ کسی لوک داستان کو اسٹیج پر پیش کرتے تھے اسی وجہ سے ان کی اداکاری میں ایک اعتماد اور گہرائی پیدا ہو جاتی تھی۔ اکثر ہی یوں ہوتا کہ رات کی کسی گھڑی میں جاکر کردار اور اداکار کا باہمی فرق مٹ جاتا اور اسٹیج پہ کھڑا پنجاب کا گھبرو اپنے آپ کو سچ مچ کا رانجھا سمجھ کے ہیر کی یاد میں کوُکنے لگتا۔ تیسری بات جو دیہاتیوں کو باندھے رکھتی وہ اس داستان کی موسیقی ہوتی۔ تھیئٹر کمپنی کے اپنے ہی موسیقار ہوتے تھے اور گیت لکھنے والے بھی۔ اس لیے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا تھیئٹر پلے میں کوئی ریکارڈ کیا ہوا گیت چلایا جائے گا۔ ہیر رانجھے کے کھیل کے لیے اگرچہ ہیر وارث شاہ سے کچھ مدد لی جاتی تھی مگر اسے بھی اپنی بنائی ہوئی دھن میں مقامی گلوکاروں سے ہی گوایا جاتا تھا۔ داستان میں جس جگہ گیت، قوالی، دوہے، ماہئیے یا ٹپّے کی ضرورت پیش آتی، بیک اسٹیج پہ موجود سازندے اور گلوکار یہ ذمہ داری براہ راست سرانجام دیتے اور کھیل کی رنگینی کو چار چاند لگا دیتے۔ ایک ہی رات میں لوگ کئی بار ہنستے اور کئی کئی بار روتے۔ یہی رونا اور ہنسنا ان کے سادہ دلوں کو مزید اُجلا کر دیتا اور یہی اُجلا پن سارا سال ان کے عمومی برتاؤ، بول چال اور میل ملاپ میں جھلکتا رہتا۔ پوری رات چلنے والا یہ کھیل کبھی صبح پانچ بجے ختم ہو جاتا اور کبھی چھ بجے۔ اباّ جی بتاتے تھے کہ ایک دفعہ تو صبح کے آٹھ بج گئے، سورج نے دھوپ کا تنبو ہر طرف پھیلا دیا مگر داستان چلتی رہی اور لوگ انت دیکھے بغیر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ گاؤں کی زندگی میں ویسے بھی کسی کو جلدی نہیں ہوتی اور وہ تو زمانہ ہی سکون اور شانتی کا تھا چنانچہ آٹھ بجے شو ختم ہوا اور پھر ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کو لوٹا۔
اباّ جی پورے زور شور سے جب یہ داستان اپنے سات آٹھ سال کے بچے کو سنا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں جہاں چمک تھی وہاں مایوسی بھی جھلک آتی تھی۔ اب میں اس لمحے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ سب کچھ کسی قید میں ڈالے ہوئے مغل شہنشاہ اور اس کے بیٹے کی داستان لگتا ہے۔ مغل شہنشاہ اپنے شاندار ماضی کی کہانی سناتے ہوئے پرجوش تو تھا ہی مگر بیچ بیچ میں کسی خاموش خیال کا جھونکا اسے اداس بھی کر جاتا تھا۔ سات آٹھ سال کا شہزادہ آنکھوں کا یہ منظر بھی حافظے میں محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو شاید اس تشبیہ پہ ہنسی آئے مگر ہر شخص اپنی ذات کو محورِ کائنات سمجھتا ہے اور اس کی اپنی ایک الگ دنیا اور جاگیر ہوتی ہے۔ میرے والد کے پاس بھی ایسی ہی ایک جاگیر تھی جس میں کھیل تماشے تھے، آزادی تھی، بھائی چارہ تھا، کھیت کھلیان تھے، ثقافت کے اظہار پر پابندی نہیں تھی، سانس لینے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی تھی اور کہیں سے بھی جان کا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ جس وقت وہ مجھے یہ کہانی سنا رہے تھے تب تک ان کی آدھی سے زیادہ جاگیر لوٹی جا چکی تھی اور وہ مجھے ایک ہارے ہوئے مغل بادشاہ ہی لگ رہے تھے۔
میں نے پوچھا کہ اب یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس سوال پر گہری سانس کے پسِ منظر میں انہوں نے کہنا شروع کیا: جنرل ضیاء الحق کا دور جب شروع ہوا تو ان میلوں ٹھیلوں اور کھیل تماشوں کی نئے سرے سے تشریح شروع ہوگئی۔ کئی چیزیں جو اس سے پہلے ہم ہنستے کھیلتے کر گزرتے تھے اب وہ غیر شرعی اور غیر اسلامی قرار دی جانے لگیں۔ میلوں نءؓ پولیس بھی تعینات ہونے لگی اور ایک ایک کرکے ‘مخرب الاخلاق’ تمام سرگرمیوں کو تلف کیا جانے لگا۔ کلچر کی نئی تعریف و تشریح شروع ہو گئی۔ ناچ گانا قابلِ تعزیر ٹھہرایا گیا تو یہ تھیئٹر کمپنیاں بھی بند ہونے لگیں۔ ورائٹی شو ختم ہو گئے لیکن ‘موت دے کھوہ’ والا کھیل جاری رہا۔ اب میلہ کیا تھا ایک بے رونق سا اکٹھ ہونے لگا کیونکہ بہت ساری سرگرمیاں جو پہلے صحت مند سمجھی جاتی تھی اور ایسے میلوں کی پہچان ہوتی تھیں اب ان سے نظریاتی بنیادوں کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا اور انہیں یکسر غیر شرعی قرار دے کر دائرہ اسلام اور دائرہ ثقافت سے خارج کر دیا گیا تھا۔ گیارہ سال میں تھیئٹر والے، گانے والے، نقلیں کرنے والے، بازی گر، شعبدہ باز، ورائٹی شو والے اور ایسے ہی کتنے لوگ پہلے تو چپ چاپ گھروں میں بیٹھ گئے اور پھر جب جان کے لالے پڑے اور بھوک نے ستایا تو اپنا اصل کام چھوڑ چھاڑ کر کسی نے دکان ڈال لی، کوئی خلیجی ملکوں میں جاکر بھٹک گیا، کوئی مزدوری کرنے لگا اور کوئی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس مرنے کے لیے دستیاب ہوگیا۔ غرضیکہ وہ لوگ جو مقامی تھیئٹر اور میلوں کی جان تھے وہ اب متنازع بن کر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کالی آندھی کے سائے جب چھٹے اور ملک میں جمہوریت اس بے یقینی سے سہمی سہمی آئی جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکے گی تو حالات نے کروٹ لی۔ گیارہ سال کی ‘ترقی’ کا ملبہ ہٹانا کوئی ایسا آسان کام نہ تھا کہ دو چار مہینوں میں ہی سب کچھ اصل حالت میں لوٹایا جا سکتا۔ ضیاء ہی گیا تھا مگر اس کی سوچ تو قبولیت پذیری کی حدیں چھُو رہی تھی اور پوری طرح موجود تھی۔ چنانچہ جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب 77ء سے پہلے والا پاکستان لوٹ آئے گا وہ بے چارے میرے اباّ کی طرح ہی دل شکستہ ہوئے۔ اگرچہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کسی قدر آزاد ہو گئے، کچھ پوپ گلوکار بھی اپنے اپنے گٹار لے کر پہنچ گئے مگر بحالی کا یہ کام ادھورا ہی رہ گیا۔ بالکل اسی طرح جیسے 1947ء میں بھارت سے آنے والے مہاجرین کی آباد کاری کا کام کبھی پورا نہ ہو سکا۔ 88ء کے بعد ہانپتے کانپتے پاکستان کو اگرچہ نظریاتی تجربہ گاہ سے تو نکال لیا گیا مگر پھر یہ مسلسل اسٹریچر پر ہی رہا۔
کوشش کی گئی کہ میلے ٹھیلے پھر آباد کیے جائیں، موسیقی کو جگہ دی جائے، سلطان راہی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کے فلم انڈسٹری کا قبلہ درست کیا جائے مگر گیارہ سال کے عرصے میں کئی زرخیز لوگ ویسے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور باقی بچ جانے والوں میں سے زیادہ تر بددل ہوکر گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ اس لیے بحالئِ ثقافت کا کام کھٹائی میں پڑ گیا اور آج تک اسی کھٹائی میں ہی چل رہا ہے۔ تھیئٹر کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اباّ جی نے بتایا کہ بیٹا کوئی بھی کاروبارہ گیارہ سال کی بندش کے بعد جھٹ سے کیسے دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ وہ کمپنیاں جو کبھی ڈرامے کرتی تھیں وہ کب کی مر کھپ گئیں، فنکاروں کو ادھر ادھر چھپنا پڑا اور جہاں پہلے پانچ پانچ کمپنیاں ہر میلے میں پہنچی ہوتی تھیں اب کوئی ایک آدھ ہی نیم دلی کے ساتھ پہنچ پاتی۔ ساز ہیں تو سازندے کم پڑ رہے ہیں، کہانی ہے تو اداکار نہیں ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ کمپنیاں ختم ہو گئیں۔ کوئی اکّا دکاّ کمپنی جو پچھلے سال تک ہمارے نواحی گاؤں کے میلے میں آتی رہی تھی، مالی مشکلات یا اللہ جانے کسی اور مشکل کی وجہ سے وہ بھی اس سال میلے میں نہ آ سکی۔ اس کے بعد کسی بھی سال کوئی تھیئٹر کمپنی ہمارے میلے میں نہیں آئی اور میرا تھیئٹر دیکھنے کا خواب پھر لاہور میں آ کر ہی پورا ہوا۔
نئے دور میں اب لوگ تفریح کے بھوکے تھے، اتنے دنوں بعد تفریح پر سے پابندیاں اٹھیں تو ظاہر ہے کہ انہیں اب کچھ نہ کچھ تو چاہیے تھے۔ معیاری تفریح کے اکثر ذرائع تو اوندھے منہ پڑے تھے مگر موقع پرستوں کی ایسی بھی کوئی کمی نہیں پاکستان میں لہٰذا ناتجربہ کار لوگوں نے تفریح کے اس خلاء کو فوراً سے پہلے پُر کر دیا۔ اب پہلے جہاں تھیئٹر کمپنیاں آتی تھیں اب جابجا میلوں میں ‘سائیکل گراؤنڈ’ آنے لگے۔ سائیکل گراؤنڈ کی یہ اصطلاح ایک ایسے گروپ کے لیے مخصوص ہے جس کا سرخیل کوئی مقامی سا غیر تربیت یافتہ گوّیا ہوتا ہے اور گراؤنڈ میں گیس کے غباروں سے جلنے والی بڑی بڑی لالٹینیں روشن کرکے اپنے بے سرُے گلے سے جب وہ ہارمونیم بجا کے کچھ گانے کی کوشش کرتا ہے تو ساتھ میں چار پانچ کھُسرے اردگرد منڈلانے اور ناچنے لگتے ہیں۔ طبلے پر پڑنے والے بے ہنگم ہاتھ اور پھر بڑے بڑے سپیکروں سے کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی ان کی آوازوں میں اگر کوئی تفریح پیش کی جا رہی ہے تو اسے صحت مند ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پھر دیہاتی پس منظر کے لوگ اس حقیقت سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ ایسے سستے سستے سائیکل سٹینڈوں میں ناچنے والے کھُسرے اتنے پیسے پرفارمنس سے نہیں کماتے جتنے انہیں منچلوں کے ساتھ جنسی عمل کرکے کمانے پڑتے ہیں۔ پولیس اب بھی میلوں میں تعینات ہوتی ہے اور یہ سب کچھ ہر میلے میں چلتا ہے مگر اب کسی کے اخلاق خراب ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اب جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر سب کچھ چلایا جا رہا ہے۔ کوئی اس بارے میں نہیں سوچ رہا کہ دیہات اور چھوٹے شہروں کے عوام کو بھی سستی اور معیاری تفریح فراہم کرنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ اور ایسا کرنا کوئی مریخ پہ گھر بسانے جتنا مشکل کام نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں بے تحاشہ رقم اور بے انتہا وقت چاہیے۔ یہ ماڈل تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ مقامی طور پر تھیئٹر کمپنیوں کو شروع کیا جائے اور لوگوں کو زندہ ہونے کا احساس دلایا جائے۔
میں ایک ایسے دور کا خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرے اسی نواحی گاؤں کے میلے میں اجوکا تھیئٹر جا کر اپنے کھیل پیش کرے، فیض فیسٹیول وہاں بھی منعقد کیا جائے تاکہ آگاہی کا عمل بڑے پیمانے کو چھُو سکے اور فیض احمد فیض بھی کسی طرح ان لوگوں تک پہنچے جن کے لیے وہ ساری عمر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا رہا اور لکھتا رہا۔ فیض فاؤنڈیشن والے تو شاید اتنے پہ ہی خوش ہیں کہ انہوں نے فیض کو بڑے شہروں میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ بھئی فیض صرف لاہور یا کراچی یا اسلام آباد کا شاعر تو تھا نہیں، آپ اس طرح کا پروگرام کیوں نہیں ترتیب دے سکتے جس میں شہر شہر گاؤں گاؤں یہ فیسٹیول منعقد ہوں اور لوگ پھر ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، باہمی بدگمانیاں ختم ہوں اور فیض جیسے بڑے لوگوں کا پیغام اس کے اصل سامعین تک پہنچ سکے۔ صرف لاہور میں میلہ لگانے سے فیض جیسی بڑی شخصیت کو چند لوگوں تک کیوں محدود کرنے پر تلُے ہیں۔
میرے اباّ جی چار سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ آخر تک اپنی ثقافتی جاگیر لٹنے کے غم میں مبتلا رہے اور اس سے بھی زیادہ انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ جو بچی کھُچی جاگیر وہ اگلی نسل کو دے کے جا رہے ہیں اس پہ کوئی کیسے فخر کر سکے گا۔