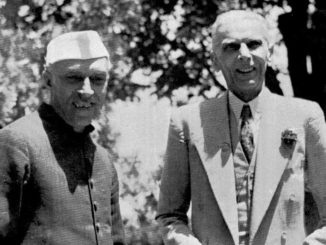سردار سریندر سنگھ سوڈی کا کٹا سر
از، خالد فتح محمد
اس قافلے میں سے زندگی کی نئی قسطیں پا جانے والوں میں آج صرف ہم تین لوگ زندہ ہیں۔
ہم زندگی کی ہر گرم سرد دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے طے کیا ہوا کہ آج کے دن تینوں کچھ وقت اپنے اس سفر اور بعد کی زندگی کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اکٹھے گزاریں گے۔
ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں؛ ایک حُقّہ گڑگڑاتا ہے، دوسرا سگریٹ پیتا ہے جب کہ میں تمباکو نہیں پیتا تھا۔
اس شام مجھے گھر سے باہر کھیلنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ گھر میں ایک طرح کی نا مانوس سی چپ اور بلیک ہول جیسے کسی کھچاؤ کی عجیب سی کیفیت تھی۔
وہ شام رینگتے رینگتے رات ہوئی۔ گاؤں کی رِیت اور حبس کے موسم کے دستور کے مطابق میں چھت پر سو رہا تھا کہ ماں نے وحشت کے عالم میں مجھے جگاتے کہا:
ذخیرے کے پاس نعرے گونج رہے ہیں اور کسی بھی وقت جتھہ پڑ جائے گا۔
ان دنوں ہم دوست کچھ دنوں سے جتھہ پڑنے کے بارے میں آپسی باتیں کیا کرتے تھے۔ ماں کے چہرے کی اُڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر میں اور بھی ڈر گیا اور متجسس بھی ہوا کہ جتھہ آخر پڑے گا کیسے۔
گاؤں کے جوانوں نے اکٹھے ہو کر ذخیرے سے آنے والے راستے پر اپنے مورچے کی دیوار کھڑی کر دی۔
ان جوانوں میں میرے دو شِیں جوان بڑے بھائی بھی تھے۔ وہ جوان ہمیں گاؤں سے بَہ حفاظت نکالنے میں کام یاب تو ہو گئے، لیکن بعد میں خبر ملی کہ سب مارے گئے تھے۔
مجھے جب ماں نے جگایا تو اتنی گھبراہٹ تھی کہ میں جوتا بھی نہیں پہن سکا تھا۔ قافلہ جب چلا تو میں ننگے پاؤں تھا۔
میرے پیروں میں چھالے پڑے، زخم بنے، کانٹے چبھے اور ایک بار سانپ نے بھی ڈسا لیکن ہم چلتے رہے۔
راستے میں کئی جتھے حملہ آور ہوئے۔ ہم میں سے چند اور مارے گئے۔ میری نانی شدید زخمی ہوئیں۔ وہ اتنی زخمی تھیں کہ سفر کی صعوبتیں اٹھانے جوگی بھی نہیں رہی تھیں۔ ان کی تجویز پر ہی انھیں وہیں چھوڑ دیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ اس فیصلے کو تجویز کرنے کے پیچھے جانے کون کون سا درد اور کیسی نفسیات تھیں!
البتہ میری ماں جب تک زندہ رہیں، یہی کہتی رہیں:
“بے بے کی آنکھوں کی شکایت کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ وہ کہہ رہی تھیں،’میں تمھیں کبھی چھوڑ کر نہ جاتی۔'”
میری ماں اسی دکھ میں مر گئیں، زیادہ نہیں جی سکیں۔
ہم چلتے چلتے، گرتے اٹھتے، چلتے رِڑتے لائل پور کے ایک گاؤں میں پہنچ گئے جو خالی تھا اور ہم جیسے پناہ گزین اسے بھر رہے تھے۔
کیا یہ وہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے؟
یقیناً نہیں۔ گھروں پر قبضہ کے لیے جھگڑے، قافلے میں ہر کوئی کسی کا پابند تھا؛ یہاں انفرادیت تھی۔
آباد کاری شروع ہوئی تو سب پیچھے جاگیریں چھوڑ کر آئے تھے۔ تحصیل دار اور ضلع دار کے پاس شکائتیں، آپسی جھگڑے … یقیناً یہ کوئی اور لوگ تھے۔ رضا کار نقدی اور اجناس دینے آتے، تو دیتے کم، رسیدیں زیادہ کی مانگتے۔
لوٹ کھسُوٹ انتہا درجے کی تھی۔ ایک انتہا اور بھی تھی۔ شاید یہ وقت تھا ہی انتہاؤں سے عبارت!
کئی لوگ ایسے بھی تھے، لیکن بہت کم، جنھوں نے وہی مانگا اور لیا جو ان کے استعمال میں تھا۔ اگر ایک گھر خالی تھا، جدّی پشتی زمین کسی وقت دریا بُرد ہو گئی تھی، البتہ کاغذات میں انھی کی ملکیت تھی، انھوں نے اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ بعد میں سننے میں آیا کوئی اور جعل سازی کے ذریعے اسے بھی لے اُڑا۔
ایک اور ابتدا جو ایک انتہا بھی تھی…!
جس مکان میں میرا خاندان رہائش پذیر ہوا وہ کچھ بہتر اور نسبتاً نیا تھا۔ اس کی تعمیر سِنہ 1923 میں ہوئی تھی۔ تعمیر کا یہ سِن چھوٹے سے برآمدے میں لکھا ہوا تھا۔ البتہ جب اس گھر میں پہنچے تو وہاں ایک خوش شکل سکھ کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔
ہمیں پتا چلا کہ وہ گھر کا مالک سردار سریندر سنگھ سوڈی تھا، جسے چند دن قبل مارا گیا تھا۔
میرے دادا نے اس سر کو، کسی کو بتائے بغیر، گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے دفن کر دیا۔
چند سالوں کے بعد ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے اور آباد کاری کے مسئلے مسائل اور گھر کی تنگی کی بات ہو رہی تھی۔ اسی بات چیت کے بیچوں بیچ لمبے، سفید کُرتے میں، ملجگی داڑھی والا ایک سایہ اچانک بیچ میں سے گزر گیا۔
ایک دم باتیں تھم گئیں، اور خاموشی اتنی کہ سانسیں بھی گِنی جا سکتی تھیں۔ سب کے ہوش بَہ حال ہوتے کچھ وقت لگا۔
خاموشی کے وقفے کو توڑتے دادا نے کہا:
“یہ سردار سریندر سنگھ سوڈی تھا۔”
گھر کی تنگی کی بات ہو رہی تھی کہ اسے گرا کر نیا گھر بنایا جائے جو کُھلا ڈُلّا ہو۔ سوڈی کو یہ سب سوچنا پسند نہیں آیا۔ وہ ہمیں ایک پیغام دینے یا درخواست کرنے آیا تھا کہ گھر میں تبدیلی نہ کی جائے۔ شاید اس نے گھر اپنی بیوی کے لیے بنایا ہو جو وہاں کہیں…، دادا نے مشرق کی طرف اشارہ کیا،”سو میری نسل اس تنگ سے گھر میں ہی رہے گی۔”
(اس کے بعد سب بابا ہی کہنے لگے تھے۔)
سوڈی کبھی کبھار، اسی وقت پہلے والی جگہ سے گزر کر سیڑھیاں چڑھ جاتے۔ وہ گھر آج تک اسی حالت میں ہے۔ ہم دادا کی وصیت کا احترام کر رہے ہیں۔
اب یہاں تقسیم شدہ دیس کی دوسری طرف کے ایک لمحے کی بات سنیے۔ ہمارے ایک عزیز کو چَڑھدے پنجاب جانے کا اتفاق ہوا تو وہ ہمارے گھر میں رہائش سکھ خاندان کی ایک ویڈیو لائے۔ ایک بزرگ سکھ کیمرے سے مخاطب تھے۔ وہ ہمارے گھر کی ویڈیو پر تبصرہ کیے جا رہے تھے۔
گھر دو بارہ بنایا گیا تھا کہ پہلے والا اسی رات جلا دیا گیا تھا۔ بزرگ سکھ نے آخر میں ہمیں مخاطب کر کے کہا:
“ہم لوگ خانیوال سے آئے ہیں۔ تم لوگ دو کام کرو۔ ایک تو میرے گھر کی تصویر بنا کر بھیجو، اور دوسرے اگر ممکن ہو تو ہمیں خانیوال بھیج دو اور خود اپنا گھر سنبھال لو۔”
میرے لیے یہ بہت بھاری امانت ہے۔ میں دونوں کام ہی نہیں کر سکا۔
تو یہ دو یادیں انتہاؤں سے لتھڑے وقت میں انسانی لمحوں کی یادگار باتیں تھیں۔ ان انسانی لمحوں کو نا جانے اوسط لمحے کہیں گے، یا صرف انسانی لمحے؟
آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آنے لگی تو ایک اور جھگڑا اُٹھ کھڑا ہوا: وہ تھا مقامی اور مہاجر کا۔
یہ کھائی تہتر برس گزر جانے کے بعد بھی نہیں بھری گئی اور جسے ملک میں ہونے والے سِنہ 1985 کے غیر سیاسی انتخابات نے مزید گہرا کر دیا۔
آج ہم تینوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2018 میں ہم چار تھے۔ گنتی کم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں کب، آج کے دن، یہاں کوئی بھی نہیں ہو گا۔
جب ہم تین نہ رہے تو یادوں کی اس زنبیل کو کون سنبھالے گا؟ اس کا وارث کون ہو گا؟ کیا ہماری یادیں کسی گُم نام سپاہی کی قبر کی طرح وقت کی گردش میں یادوں سے اوجھل ہو جائیں گی؟ شاید ہم یہی چاہتے ہیں۔ وقت تھمتا نہیں!