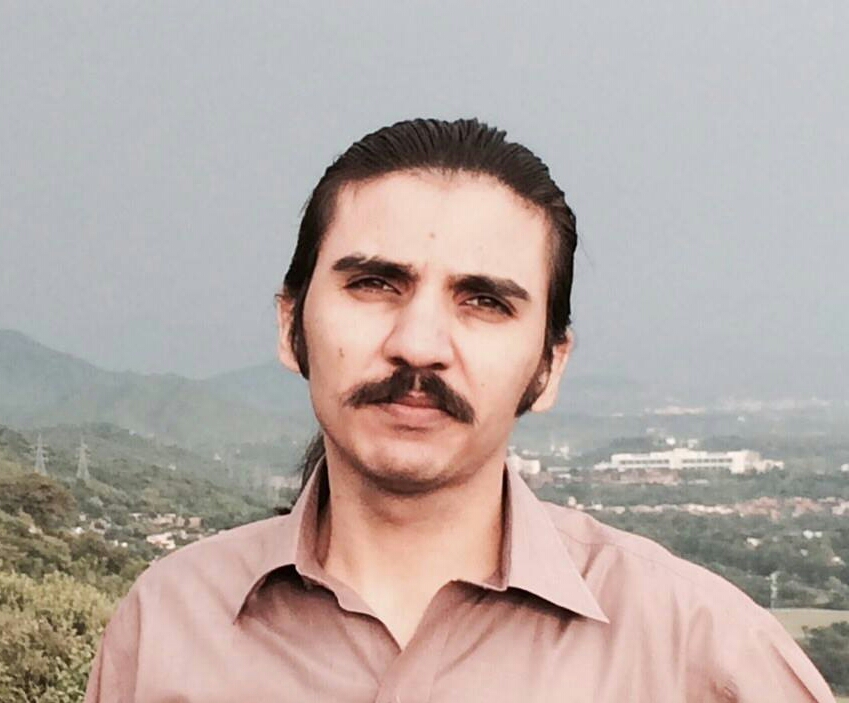جنوبی ایشیا میں فاشزم کا عروج
(سید کاشف رضا)
کراچی کے ادبی میلے میں ہر مرتبہ جو پاکستانی اکٹھے ہوتے ہیں وہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی کے سبب غیر ملکی دوستوں کے سامنے کچھ شرمندہ شرمندہ نظر آتے ہیں۔ اس مرتبہ ادبی میلے والے ہوٹل کے لان میں ایک ہندوستانی شخصیت کی باتیں سننے کا اتفاق ہوا جو بھارت میں بڑھتے ہوئے فاشزم پر پریشان نظر آتے تھے۔ مجھے ان کی باتیں سن کر ویسی ہی مسرت ہوئی جسی کسی عاشق کو یہ سن کر ہوتی ہوگی کہ حضرتِ ناصح جو انھیں عشق سے پرہیز کی نصیحت کیا کرتے تھے، وہ آج کل خود بھی عشق سے منسلک پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔
میری مسرت کا تعلق اس بات سے قطعاً نہیں تھا کہ بھارت میں فاشزم کوئی ایسی چیز ہے جو نئے نویلے عشق کی طرح حال ہی میں نمودار ہو گئی ہے، بلکہ اس بات سے تھا کہ بھارتی فاشزم کو اب ننگی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور بھارتی دانش ور اب اس سے آنکھ چرانے کے بجائے اسے ایک حقیقت تسلیم کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کسی نقصان دہ سیاسی نظریے کا مقابلہ کرنے کے لیے شرطِ اوّل یہی ہے کہ اسے کوئی موہوم سا مظہر سمجھنے کے بجائے واضح حقیقت سمجھا جائے اور اس کی اسی حیثیت کو سمجھانے کی بھی کوشش کی جائے۔
میلے کے ایک سیشن میں پاکستانی، بھارتی اور بنگلادیشی ادیب بھی موجود تھے، وہاں بھی بصد شوق گیا کہ دیکھیے بنگلادیشی ادیبہ اپنے ملک میں فاشزم کی تازہ لہر کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تاہم وہاں کتابوں کی اشاعت کے مسائل پر بات ہو رہی تھی۔
بنگلادیش میں عوامی لیگ اور اس کی لیڈر شیخ حسینہ کے ہاں فاشزم اس اعتبار سے اور بھی افسوس ناک نظر آتا ہے کہ بنگلادیش کو اپنی ریاست کے اندر ویسے متنوع مسائل اور معاملات کا سامنا نہیں ہے جیسے پاکستان یا بھارت کو ہے۔
برصغیر کا ایک اور ملک سری لنکا بھی چند ماہ پہلے صدر مہندرا راجا پاکسے جیسے مردِ آہن کے ہاتھوں میں تھا اور وہ بھی اختیارات کے اپنی ذات میں زیادہ سے زیادہ ارتکاز کے خواہش مند نظر آتے تھے۔ تاملوں پر فتح کے بعد انھوں نے ان کے لیے ویسی رواداری کا مظاہرہ نہیں کیا جس کی توقع ایک جمہوری مزاج رکھنے والے سیاست دان سے کی جانی چاہیے۔
برصغیر کی سیاست اور معاشرے میں فاشزم کے رجحان کا مطالعہ کرتے وقت سب سے اہم بات یہ پیشِ نظر رکھنی چاہیے کہ برصغیر کی تقسیم کا مطالبہ بھی اسی لیے کیا گیا تھا کہ ہندوستان کی ایک بڑی اور طاقت ور اقلیت کو یہ خدشہ تھا کہ انگریزوں سے آزادی کے بعد کانگریس ہندو اکثریت کے بل بوتے پر انھیں دبائے گی۔ یہ احساس تقسیمِ ہند سے پہلے کے مسیحیوں، اچھوتوں اور کسی حد تک سکھوں میں بھی موجود تھا۔
ان خدشات کا حل نکالنے کے ایک سے زیادہ راستے موجود تھے۔ مسلمانوں کی اکثریت نے ان میں سے ایک راستے کا انتخاب کیا اور پاکستان بنا لیا۔ اچھوتوں نے ایک اور راستے کا انتخاب کیا اور ڈاکٹر امبیدکر کی قیادت میں آئینی ضمانتیں حاصل کر لیں۔
اب بھی مسلمانوں اور اچھوتوں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اپنی اپنی کمیونٹی کے لیے منتخب کردہ حل سے مطمئن نہیں ہوں گے، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں اور اچھوتوں (اور دوسری اقلیتوں) کو اپنے روندے جانے کا خدشہ ضرور تھا اور تقسیمِ ہند کے بعد ایسے حالات باربار پیدا ہوئے جن میں ان کا یہ خدشہ درست ثابت ہوا۔
ان اقلیتوں کو یہ خدشہ ہندو اکثریت کے ہاں پائے جانے والے جس رجحان کی بنیاد پر تھا، اسی کی زیادہ واضح اور زیادہ بری صورت فاشزم ہے۔ ڈاکٹر امبیدکر نے واضح کر دیا تھا کہ قیامِ پاکستان کا مطالبہ نہ مانا گیا تو یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ ان کے خدشات ختم ہو جائیں گے۔
مطلب یہ کہ اگر پاکستان انیس سو سینتالیس میں نہ بنتا تو اس کا مطالبہ بعد میں بھی کسی نہ کسی صورت میں زندہ ضرور رہتا۔ شاید یہ بات جواہر لال نہرو اور ان سے زیادہ سردار پٹیل کی بھی نظر میں تھی، اس لیے انھوں نے ہندو مسلم تنازعے کے شکار متحدہ ہندوستان کے بجائے ایک متحد اور سینٹرلائزڈ لیکن رقبے میں مختصر ہندوستان پر اکتفا کرنا زیادہ بہتر سمجھا جس کی تعمیر و تشکیل وہ اپنے وژن کے مطابق کر سکیں۔
ڈاکٹر امبیدکر خود اپنی اچھوت کمیونٹی کے لیے ویسے ہی خدشات رکھتے تھے اور اپنی کمیونٹی کے لیے بھی الگ حق رائے دہی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انگریز بھی اس کے لیے تیار ہو گئے تھے مگر گاندھی جی کو اس مسئلے کی سنگینی کا احساس تھا۔ انھوں نے مرن برت رکھ لیا اور مدن موہن مالویہ وغیرہ نے ڈاکٹر امبیدکر کو یہ کہہ کر رام کر لیا کہ اگر گاندھی جی کا اسی مرن برت کے دوران دیہانت ہو گیا تو دلت مخالف فسادات شروع ہو سکتے ہیں۔ یوں انھوں نے ڈاکٹر امبیدکر کو دلتوں کے لیے الگ حق رائے دہی کے حصول سے باز رکھا۔
یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اگر اچھوتوں کو اپنے نمایندے الگ سے منتخب کرنے کا حق مل جاتا تو ہندوستان کی آزادی کے وقت ان کا فیصلہ کیا ہوتا مگر اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ایک برتر حیثیت سے کرتے۔ ڈاکٹر امبیدکر کو جیسی جذباتیت سے رام کیا گیا ویسی جذباتیت سے انگریزی طرزِ فکر کے حامل جناح کو متاثر کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا۔
ڈاکٹر امبیدکر نے مسلم لیگ کی جانب سے قیامِ پاکستان کے مطالبے کے فوری بعد ایک کتاب لکھی تھی جس کا عنوان تھا: پاکستان یا تقسیمِ ہند۔ اس کتاب میں انھوں نے مسلمانوں کے خدشات کو جینوئن قرار دیا تھا۔ انھوں نے اپنی اس کتاب میں دلائل اس بنیادی نکتے سے اٹھائے کہ ایک متنوع معاشرے میں کوئی کمیونٹی صرف اس بنیاد پر مسلسل شکرگزار نہیں رہ سکتی کہ اسے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی فراہم کر دی جاتی ہے۔ اس کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے معاشرے میں ’حاکم نسل اور محکوم نسل‘ کا تصور موجود نہ ہو اور اسے ریاست کے ہر اہم فیصلے میں شراکت کا احساس ہو۔
ڈاکٹر امبیدکر کا خیال تھا کہ ان کے ہندوستان میں ’حاکم نسل اور محکوم نسل‘ کا تصور پوری طرح موجود تھا اور گاندھی جی کی رواداری اور جواہر لال نہرو کے سیکولرازم کے باوجود ان کا خیال یہ تھا کہ ’’کانگریس اپنی ہندو ذہنیت اور ہندو اندازِ فکر کے اظہار پر مجبور ہے۔ کانگریس اور ہندو مہاسبھا میں محض ایک فرق ہے کہ فریقِ دوم اپنی گفتار میں کھردرا اور اپنے عمل میں ظالم ہے جب کہ کانگریس سیاسی زبان بولتی ہے اور نرم خو ہے۔‘‘
دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے پاکستان حاصل کر لیا تو اکثریت کی جانب سے روندے جانے کا یہی خدشہ پہلے مشرقی پاکستان اور بعد میں باقی ماندہ پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں بھی پیدا ہوا۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کو باقی پاکستان پر آبادی کے لحاظ سے بھی برتری حاصل تھی مگر اسے اس آبادی کے تناسب سے اقتدار میں حصہ نہیں مل رہا تھا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ’روندے جانے کے خدشے‘ کے لیے کسی کمیونٹی کا عددی اقلیت میں ہونا بھی ضروری نہیں۔
لیکن اہم بات یہ ہے کہ فاشسٹ رجحان ہمارے معاشرے میں اس حد تک رچے بسے ہیں کہ ایک کمیونٹی، جو خود کسی دوسری کمیونٹی کے ہاتھوں روندے جانے کے خدشے سے دوچار رہی ہو، جب خود طاقت حاصل کر لیتی ہے تو اپنے چھوٹے گروہوں کے ساتھ کسی قسم کی فیاضی کا مظاہرہ نہیں کرتی۔
آج کا پاکستان اس سلسلے میں ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ تین چھوٹے صوبے ایک بڑے صوبے پنجاب کی شکایت کرتے ہیں مگر اپنے صوبے میں موجود چھوٹی لسانی اکائیوں کے لیے ویسی رواداری نہیں دکھاتے جیسی رواداری کے وہ خود پنجاب سے طالب ہیں۔
سندھ کی حکم راں پیپلز پارٹی شہری علاقوں میں بسنے والے مہاجرین کی اولادوں سے تعصب برتتی ہے اور فریقِ ثانی کی نمایندہ تنظیم متحدہ قومی موومنٹ کو کراچی میں پشتونوں کی بڑھتی ہوئی آبادی گوارا نہیں اور وہ کراچی کا بلاشرکتِ غیرے مالک بننا چاہتی ہے۔
متحدہ ہندوستان دنیا بھر میں اپنے لسانی، نسلی اور مذہبی تنوع کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم سب اس تنوع، اس رنگارنگی کو فخر کے ساتھ دنیا بھر کے سامنے پیش کرتے۔ مگر ہم ایک دوسرے کے حوالے سے اپنی نفرتیں، اپنے خدشات ختم یا کم نہ کر سکے۔ ہم تین ملکوں میں تقسیم ہو چکے اور ان تقسیم شدہ ملکوں میں بھی خود کو مختلف گروہوں میں بانٹ کر بیک وقت اپنا تحفظ کرنے اور دوسرے گروہوں کو نیست و نابود کرنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ ایسے میں معاشرہ فاشسٹ رجحانات کا نمایندہ بن جائے تو اس میں امریکا وغیرہ کی سازش کو دوش کیا دینا۔ یہ تو ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔
ایک دوسرے کے لیے عدم برداشت کا رویہ ہمارے برصغیر کے عوام کی جبلت میں موجود ہے اور اس کے تدارک کے لیے گاندھی جی کا اہنسا کا فلسفہ ناکافی ثابت ہوا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک گاندھی جی کے مقابلے میں یہاں کئی ایسے مولانا اور تپسوی مہاراج موجود رہے ہیں جو عوام کے سستے قسم کے جذبات اور جبلتوں کی نمایندگی کرتے ہیں اور مرکزی رہ نماؤں کو بھی جب پاپولر پالیٹیکس کے لیے کوئی چال چلنا ہوتی ہے تو وہ اکثر و بیش تر انھی مہروں کو آگے بڑھاتے ہیں۔
آج ہم اپنی تحریک آزادی کے دور کے تقریباً ہر سیاست دان کے لیے سراپا احترام ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ انھی سیاست دانوں کی سیاست میں ڈاکٹر امبیدکر کو حاکم نسل سے وابستگی کا احساسِ تفاخر نظر آیا تھا جس کی بدولت اقلیتی کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے افراد کئی طرح کے خدشات کا شکار تھے۔ اس لیے تحریک آزادی سے وابستہ تمام سیاست دانوں کا بھی غیر جذباتی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہماری تعمیر میں خرابی کی کتنی صورتیں مضمر ہیں۔
جنوبی ایشیا میں فاشسٹ رویوں کا مطالعہ کرتے وقت اس خطے کی خون آلود اور حسرت ناک تاریخ میں مرکزی کردار ادا کرنے والے سیاست دانوں کا نفسیاتی مطالعہ، بہت سی گرہیں کھول سکتا ہے۔ ان سیاست دانوں کی شخصیتوں میں پیچ تو اور بھی ہوں گے، جنھیں دریافت کرنا ان کا کام ہے جو تاریخ اور نفسیات دونوں شعبوں میں مہارتِ تامہ رکھتے ہوں۔
میں تو فی الحال ان سیاست دانوں کے دو رجحانات پر روشنی ڈالنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ پچھلے کئی عشروں کے دوران جنوبی ایشیا کے سیاست دانوں میں خود کو دیوتا، انسانِ کامل، مردِ آہن وغیرہ کہلانے کا شوق تو بڑھتا چلا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب وہ تاریخ کے اہم ترین مراحل پر مختلف تنازعات کو حل کرنے کی کوششوں میں باربار ناکام ثابت ہوئے ہیں۔
برصغیر کی تقسیم کے دوران ہندوستان میں گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور محمد علی جناح جیسے لیڈر موجود تھے جنھوں نے اپنی عمریں جمہوری جدوجہد میں صرف کی تھیں۔ تقسیمِ ہند کے بعد گاندھی جی جو ساڑھے پانچ ماہ زندہ رہے ان کے دوران ان کے جمہوری رویے اور بھی نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ وہ ہندو مسلم فسادات کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور انھوں نے پاکستان کو اس کے اثاثے دینے کے لیے بھی پرزور مطالبہ کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ گاندھی جی نے تقسیمِ ہند کے بعد اقتدار میں براہِ راست حصہ قبول نہیں کیا تھا۔ وہ برصغیر کی آزادی کے بعد صرف ساڑھے پانچ ماہ زندہ رہے اور یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ مزید زندہ رہتے تو اپنے اصولوں پر کس حد تک کاربند رہتے۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی جان اس وجہ سے لی گئی کہ وہ مسلمان اقلیت کے تحفظ کی بات کرتے تھے۔
گاندھی جی نے تحریکِ خلافت کے دوران جذباتی مسلمانوں کے ان مطالبات کی بھی حمایت کی جو جدید نظریات رکھنے والے مسلمانوں اور خود ترکوں کو بھی قبول نہیں تھے۔ ڈاکٹر امبیدکر نے اپنی کتاب میں گاندھی جی کی جانب سے مسلمانوں کی حد سے زیادہ حمایت پر حیرانی کا بھی اظہار کیا ہے اور یہ ڈاکٹر امبیدکر وہ ہیں جو خود مطالبہء پاکستان کی حمایت کر چکے تھے۔
اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت انھیں اپنا رہ نما تسلیم نہ کر سکی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید جب ایک عام مسلمان انھیں مختصر سی دھوتی اور چادر میں لپٹا، مندروں میں شب و روز گزارتا، گائے اور بکری کی تعظیم کرتا اور برت رکھتا دیکھتا ہوگا تو وہ خود کو ان سے الگ محسوس کرتا ہوگا۔
گاندھی جی اپنے لباس، وضع قطع اور طور طریقے سے ہندوستانی نظر آنا چاہتے تھے، مگر مسلمانوں کو وہ ایک ہندوستانی کے بجائے ہندو ہی نظر آتے ہوں گے۔ انھوں نے شمالی برصغیر کی مشترکہ زبان کو ’ہندوستانی‘ کا نام دینے کی کوشش کی، مگر تب تک ایک ہی زبان کے دو مختلف ادب پیدا ہو چکے تھے، وہ دونوں کو ایک نہ کر سکے۔
دیوناگری حروفِ تہجی سے ابتدائی نوعیت ہی کی آگاہی حاصل کر کے مجھے معلوم ہوا کہ یہ حروفِ تہجی اردو الفاظ کے تلفظ، خصوصاً زیر، زبر اور پیش کو زیادہ واضح طور پر ادا کرنے کے قابل ہیں۔ مگر اس کے باوجود میں اردو حروفِ تہجی کے دائروں اور قوسوں کی محبت اور کشش کو اپنے دل سے نکالنے سے قاصر ہوں۔
عام مسلمان کے لیے بھی دیوناگری لپی کو قبول کرنے کا تصور ناقابلِ فہم رہا ہوگا۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید گاندھی جی کے سیکولر ازم کے بجائے برصغیر کے لیے جواہر لال نہرو کی شیروانی اور محمد علی جناح کا سوٹڈ بوٹڈ سیکولرازم زیادہ مناسب تھا۔
نہرو اور جناح کم از کم اپنے طرزِ زندگی میں تو گاندھی جی سے زیادہ سیکولر نظر آتے تھے۔ جناح کا تو گاندھی جی سے ابتدائی اختلاف بھی اس بات پر ہوا تھا کہ مذہب کو سیاست میں نہ لایا جائے۔ لیکن تضاد یہ ہے کہ اختیار ملا تو نہرو اور جناح تاریخ کے سامنے اس طرح سے سرخ رو نہ ہو سکے جس طرح گاندھی جی ہوئے تھے۔
محمد علی جناح نے تمام عمر قانون پسندی اور جمہوریت کا پرچار کیا۔ جمہوریت میں ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر انھیں برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق محفوظ نظر نہ آئے تو قیامِ پاکستان کی تحریک چلائی اور پاکستان حاصل کر لیا، مگر پاکستان میں انھوں نے اسی جمہوریت کے تحت دیگر مذہبی اکائیوں کو برابر کا شہری تسلیم کرنے کا بھی اعلان کیا جس کا ذکر گیارہ اگست انیس سو سینتالیس کی ان کی مشہور تقریر میں بھی موجود ہے۔
انھوں نے اپنی قانونی جدوجہد کے دوران سندھ، شمال مغربی سرحدی صوبے اور بلوچستان کے حقوق کے لیے بھی بہت جدوجہد کی تھی۔ آزادی کے بعد انھیں صرف تیرہ ماہ ملک چلانے کا موقع ملا۔ اس دوران انھوں نے قیامِ پاکستان کے صرف سات روز بعد بائیس اگست کو شمال مغربی سرحدی صوبے میں ڈاکٹر خان کی منتخب حکومت کو ہٹا دیا کیونکہ وہ کانگریس کی حامی تھی۔
آٹھ ماہ بعد سندھ میں ایوب کھوڑو کی حکومت بھی ہٹا دی گئی۔ قائدِاعظم بلوچستان کو دیگر صوبوں کے برابر حقوق نہ دلا سکے اور مشرقی بنگال کے عوام کی آرزوؤں کے برخلاف صرف اور صرف اردو کو پاکستان کی واحد قومی زبان قرار دیا۔ دوسری جانب وہ ملک کو ایک متفقہ آئین دلانے کی جانب بھی پیش رفت نہ کر سکے، تاہم اس سلسلے میں اگر وہ کوئی کوشش کرنا بھی چاہتے تھے تو ان کی خرابی ء صحت نے انھیں اس کا موقع نہ دیا۔
بھارت میں جواہر لال نہرو کو اقتدار ملا تو انھوں نے چند ہی برسوں میں ملک کو ایک متفقہ آئین دیا۔ ہندوؤں کے اندر بڑی اور چھوٹی ذاتوں کا مسئلہ بھی ہندو مسلم کمیونل مسئلے کی طرح قابو سے باہر ہو سکتا تھا، مگر نہرو نے آئین بنانے کی ذمہ داری ہی ایک دلت رہ نما ڈاکٹر امبیدکر کو سونپ دی تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے جیسی آئینی ضمانتیں چاہیں، خود لکھ کر حاصل کر لیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان ضمانتوں پر ان کی روح کے مطابق عملدرآمد نہ ہو سکا اور ڈاکٹر امبیدکر کو ہندو مت چھوڑنا پڑا۔
جواہر لال نہرو نے ملک کے طول و عرض میں پھیلی ریاستوں اور رجواڑوں کو بھی یونین میں ضم کیا اور یوں ان کے عوام کو بھی جمہوریت سے فیض یاب ہونے کا موقع دیا۔ لیکن وہی نہرو کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل سے متعلق کوئی بھی رائے دینے کی اجازت نہ دے سکے۔ انھوں نے متعدد مرتبہ یہ عزم تو دہرایا کہ کشمیری اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں گے، مگر آزادی کے بعد مزید سترہ سال وزیرِ اعظم رہنے کے باوجود انھوں نے یہ مسئلہ حل نہ کیا۔
تحریکِ آزادی کے کچھ بڑے رہ نما تو ان کی زندگی میں وفات پا چکے تھے لیکن کئی ابھی حیات تھے، مگر انھوں نے اقتدار میں آنے کے لیے اپنی بیٹی اندرا گاندھی کی راہ ہموار کی۔
بنگلادیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان نے بھی جمہوریت کو ہی اپنا رہ نما اصول قرار دیا تھا اور مغربی پاکستان کی غیر منتخب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے اصولوں کی بنیاد پر جدوجہد کی تھی۔ لیکن جب ملک بن گیا تو انھوں نے وہاں ایک پارٹی کی آمریت قائم کر دی۔ جب کسی ملک میں تبدیلی کے قانونی راستے بند کر دیے جاتے ہیں تو تشدد جنم لیتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان ایسے ہی تشدد کا شکار ہوئے اور پھر ان کا ملک پے در پے آمریتوں کے شکنجے میں جکڑا گیا۔
یہ تھے ہمارے بانیان کے رویے جن میں اقتدار و اختیار کے حصول کے فوری بعد جوہری تبدیلی رو نما ہو گئی تھی۔ برصغیر کے تین ملکوں میں جو جمہوری روایات کا زوال نظر آتا ہے تو اس کے ڈانڈے ان تینوں ملکوں کے بانیان کی شخصیت میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تاہم یہ بانیان کچھ دیگر رہ نماؤں سے بہرحال بہت بہتر تھے جنھوں نے برصغیر میں فاشسٹ رویوں کو فروغ دیا۔
ان کے لگائے ہوئے پودے تقسیمِ ہند کے وقت ایسے تنومند نہیں تھے جیسے آج نظر آتے ہیں مگر ان کے پیدا کردہ وسوسے اور خدشات اُس دور میں بھی اتنے گہرے ثابت ہوئے کہ کانگریس، گاندھی جی اور جواہر لال نہرو کی سیکولر سیاست سے ان کا مداوا نہ ہو سکا۔ یہ زمرد بھی حریفِ دمِ افعی نہ ہوا۔
تقسیمِ ہند سے پہلے کی ہندو مسلم مخاصمت کے لیے مسلمان کچھ کانگریسی رہ نماؤں کے ساتھ ساتھ ہندو مہاسبھا اور اس کے لیڈر ویر ساورکر کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ساورکر کو گاندھی جی کے قتل کے بعد بھی شاملِ تفتیش کیا گیا اور بعد میں بھی کئی مرتبہ گاندھی جی کے قتل کی سازش کا پنڈورا بکس کھلا۔
ساورکر نے ہندوتوا کا نظریہ پیش کیا اور لفظ ’ہندو‘ کو وہ مذہبی کے بجائے تہذیبی معنوں میں لیتے تھے اور ’ہندوتوا‘ میں سکھ مت، بدھ مت، جین مت اور ہندوستان کے بے خدا قبائل کو بھی شامل قرار دیتے تھے۔ وہ خود تو کسی خدا یا بھگوان کے وجود پر یقین نہیں رکھتے تھے مگر مسلمانوں اور مسیحیوں سے اس بنیاد پر پرخاش رکھتے تھے کہ ان کے مذاہب کی ابتداء ہندوستان کی جغرافیائی حدود سے باہر ہوئی تھی۔
انھوں نے اچھوتوں سے امتیازی سلوک ختم کرنے کی بھی حمایت کی مگر ڈاکٹر امبیدکر اپنی کتاب میں ساورکر کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ان کے نظریات اور پرعزم اندازِ زیست میں جرمنی کے نازیوں سے مماثلت نظر آتی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ساورکر کی اعلانیہ مداح ہے۔ اگر ہندوستان میں صرف ہندو ہی بستے تو ساورکر کے نظریات اپنے ملک کو متحد، منظم اور پرجوش بنانے کے کام آتے، مگر ایک متنوع معاشرے میں یہ نظریات انتشار کا سبب بنے۔
لیکن ویر ساورکر ایک ادیب بھی تھے اور میں جب ان کے نظریات کے بارے میں پڑھتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں جن کے نظریات اور شاعری میں مسلمانوں کو خصوصی حیثیت حاصل ہے اور وہ کارگاہِ حیات کی کپتانی مسلمانوں کو سونپنے کے خواہاں نظر آتے ہیں اور کائنات کے رازوں کی کھوج میں بھی انھی کو روانہ کرنا چاہتے ہیں۔
ایک مرتبہ فراق گورکھپوری نے کہا تھا کہ انھیں سمجھ نہیں آتی کہ علامہ اقبال کی شاعری کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے۔ فراق اردو شعری روایت میں سرتاپا رنگے ہوئے تھے اور جس کسی نے ان کی تنقیدی کتاب ’اندازے‘ کا مطالعہ کیا ہے وہ گواہی دے سکتا ہے کہ اردو کی کلاسیکی شاعری کے جیسے پارکھ وہ تھے، ان کے زمانے میں شاید ہی کوئی اور ہوگا۔ اگر وہ علامہ اقبال کی شاعری سے مرعوب نہیں ہوئے تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔
شاید نوبیل پرائز دینے والوں نے بھی علامہ اقبال کو ایسی ہی نظر سے دیکھا ہو۔ یہ بات علامہ اقبال کے مسلمان قارئین کو آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ ساورکر کے مسلمان مخالفین کہتے ہیں کہ ساورکر کو صرف بھارت ورش پر نمو پذیر ہونے والے مذاہب قبول تھے۔ اقبال کے ہاں ہندو فلسفے سے شیفتگی کے بھی آثار ہیں اور انھیں ادیب ساورکر کے ساتھ کھڑا کرنے کی ذرا سی بھی کوشش پر مجھ سمیت سبھی اردو والے ناک بھوں چڑھائیں گے مگر ساورکر کا کوئی فارسی داں حامی اقبال کے حامیوں کو شیخ سعدی کا یہ شعر ضرور سنا سکتا ہے:
گر کند میل بہ خوباں دلِ من، عیب مکن
کاین گناھیست کہ در شہر شما نیز کنند
انگریزوں کی حاکمیت کے زمانے میں ہندو،
مسلم، سکھ اور اچھوت سبھی محکوم تھے۔ ان تمام گروہوں کے قائدین نے ان کی بیداری کی تحریکیں بھی چلائیں۔ لیکن ایک کثیر لسانی اور کثیر مذہبی معاشرے میں یہ تحریکیں ایک دوسرے سے مسابقت کی دوڑ میں شامل ہو گئیں اور شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے اپنے گروہ کی برتری اور تفوّق کی کوشش کرنے لگیں۔
پہلی عالمی جنگ کے آس پاس دادا بھائی نورو جی کی قیادت کے زمانے میں انگریزوں سے آزادی کا جو خواب سب نے مل کر دیکھا تھا، اسے سب اپنے اپنے قبیلے میں بٹ کر دیکھنے لگے۔ ان تحریکوں کے بیج آج تناور درخت بن چکے ہیں اور پاکستان اور ہندوستان میں کہیں سیاہ اور ہرے اور کہیں زعفرانی رنگ میں نظر آتے ہیں۔ یہ تحریکیں آج ہمارے خطے میں فاشزم کی سب سے بڑی نمایندہ بن چکی ہیں۔
متحدہ ہندوستان میں ہندو مسلم کمیونل مسئلہ کا ایک حل ہندوستان کی دو حصوں میں تقسیم تھا۔ اس حل کو آزمانے سے کیا کمیونل مسئلہ حل ہو گیا؟ تضاد یہ ہے کہ برصغیر کے مسلمان جو خود کو ایک قوم کہتے تھے، وہ تو آج تین ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن ہندو، جنھوں نے ایسا دعویٰ نہیں کیا تھا وہ ہندوستان میں ہی رہتے ہیں اور پاکستان اور بنگلادیش سے بھی ان کی غالب اکثریت ہندوستان آ چکی ہے۔
تقسیمِ ہند کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنے اپنے ملک میں واضح اکثریت حاصل ہو گئی تو انھوں نے اپنی اپنی اقلیتوں سے ایسا سلوک نہیں کیا جس کی بنیاد پر یہ اقلیتیں مطمئن ہو سکتیں۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ برصغیر کے کمیونل مسئلے کی کچھ نئی جہتیں سامنے آ گئیں جو دونوں ملکوں کے معاشروں کو فاشسٹ رویوں کی جانب لے گئیں۔ بقیہ ہندوستان میں ہندوؤں کا تناسب اور بھی زیادہ ہو جانے کے بعد بھارتی نیشنل ازم کے نام پر ایسے رویے فروغ پانے لگے جن کے ڈانڈے ساورکر کی فکر سے ملتے تھے اور جن رویوں کو تقسیمِ ہند سے پہلے کے زمانے میں کانگریسی لیڈر بھی اس خیال سے قبول نہیں کرتے تھے کہ اس سے ملک کی مسلمان اقلیت کی دل آزاری ہو گی۔ دوسری جانب پاکستان، جو برصغیر میں اسلامی تہذیب کے تحفظ اور بقا کے نام پر حاصل کیا گیا تھا وہاں اسلامی شریعت کے تحفظ اور نفاذ کا سوال اٹھا کر ’پاکستان کا مطلب کیا، لاالٰہ الاللہ‘ کا نعرہ لگایا گیا۔
مسلمانوں کے ہر فرقے کے پاس شریعت کی اپنی تعبیر موجود تھی اس لیے اس بحث نے پاکستان میں فرقہ وارانہ سر پھٹول کو جنم دیا۔ قیامِ پاکستان کے لیے سارے مسلم فرقے متحد تھے اور اس کی تحریک میں سنیوں کے ساتھ ساتھ شیعہ اور احمدی بھی شامل تھے۔
مگر قیامِ پاکستان کے بعد پہلے احمدیوں کو کافر قرار دینے کی تحریک چلائی گئی اور پھر تکفیر پسندوں نے شیعوں کو بھی کافر قرار دے دیا۔ دیوبندیوں اور بریلویوں کا مناقشہ بھی زیادہ شدت سے ابھر کر سامنے آیا۔ ایسے میں مسلم فاشزم کی وہ صورت سامنے آئی جو آج طالبان، لشکرِ جھنگوی اور دیگر شدت پسند گروہوں کی شکل میں نظر آتی ہے۔
برصغیر کے تین ملکوں کے بانیوں کے کچھ شخصی تضادات کی جانب میں نے ایک ذرا سا اشارہ کرنے کی جسارت کی ہے۔ بانیان کے بعد آنے والے رہ نماؤں کے ہاں یہی تضادات پھلے پھولے اور برصغیر کی تاریخ جمہوریت اور اس کے لوازمات سے روگردانی کا نمونہ بن گئی۔ بعد کے دور میں برصغیر میں مختلف سیاست دانوں نے عروج حاصل کیا اور پھر جمہوری رویے اپناتے ہوئے اپنی جماعتوں کو مضبوط کرنے کے بجائے اپنا پرسنالٹی کلٹ تشکیل دینے اور اپنا سیاسی ورثہ کسی اور لیڈر کو سونپنے کے بجائے اپنی اولاد کو منتقل کرنے کو ترجیح دی۔
پاکستان میں جناح اور بھارت میں گاندھی جی کا پرسنالٹی کلٹ تو بنا لیکن دونوں نے اپنی سیاسی وراثت اپنی اولادوں کو منتقل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تاہم نہرو نے اپنے سامنے اپنی بیٹی اندرا گاندھی کی سیاسی پرورش کی اور اندرا نے پہلے اپنے بیٹے سنجے اور پھر دوسرے بیٹے راجیو کو آگے بڑھایا۔
پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد لوگ ان کے اہلِ خانہ پر ہی اعتماد کر سکتے تھے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھٹو نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی بے نظیر بھٹو کی سیاسی تربیت شروع کر دی تھی اور شملہ معاہدے سمیت کئی اہم مواقع پر بھٹو نے اپنی بیٹی کو آگے آگے رکھا تھا۔ آج پاکستان میں بے نظیر کے بیٹے بلاول پارٹی قائد ہیں اور بھارت میں کانگریس قیادت کے لیے راجیو کے بیٹے راہول کی راہ تک رہی ہے۔
بنگلادیش میں شیخ مجیب کے بعد ان کی بیٹی نے ان کا سیاسی ورثہ سنبھالا تو صدر ضیاء الرحمان کے بعد ان کی اہلیہ نے ان کی گدی سنبھالی۔ سری لنکا میں بھی بندرانائیکے خاندان سیاست میں پیش پیش رہا۔ ایسے میں پاکستان، بھارت، بنگلادیش اور سری لنکا کی جمہوریت بھوٹان کی بادشاہت سے مختلف نظر نہیں آتی۔
سوال یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں صرف وراثت کی بنیاد پر قائد بننے والوں کی قائدانہ صلاحیتیں کیا عام لیڈروں سے زیادہ ہوتی ہیں؟
جس ملک اور جس معاشرے میں صلاحیتوں کے باوجود آگے بڑھنے کا موقع نہ ملے، میرٹ کے بجائے پدرم سلطان بود کا اصول چلتا ہو، کلرک کے بچے کو صرف وہی تعلیم میسر ہو جسے پا کر وہ بھی صرف کلرک بن سکے، عوام کو زندگی کے بنیادی حقوق روٹی، کپڑا اور مکان میسر نہ ہوں، معاشرے میں کہیں بے انصافی ہو تو انصاف دلانے کے لیے کوئی قابلِ اعتبار ادارہ نہ ہو، تو معاشرے میں بے چینی اور غصہ جنم لیتا ہے۔ ایسے میں لوگ کسی مردِ کامل کی راہ دیکھنے لگتے ہیں جو ایک سہانی صبح انھیں ان کے تمام غموں سے نجات دلائے گا۔
مگر ہوتا یوں ہے کہ مردِ کامل کے اردگرد موجود لوگ اسے آسمان پر چڑھا جاتے ہیں اور کچھ مردِ کامل کو بھی اپنے کامل ہونے کا یقین ہونے لگتا ہے۔ سو یہ مردِ کامل عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے نرگسیت کے سمندر میں غوطے ہی کھاتا رہتا ہے۔ نرگسیت مغربی سیاست دانوں میں بھی پائی جاتی ہوگی لیکن وہاں کی سیاسی جماعتوں پر کسی فرد کا غلبہ چند سال تو ہو سکتا ہے، عمر بھر نہیں۔ ہمارے ہاں کے مردِ کامل تو اپنی وفات پر ہی اپنی خدمات سے دست کش ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی اکثر اپنی اولاد کو ہماری رہ نمائی کے لیے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔
پاکستان میں تو چار عدد ایسے مردِ کامل ایسے بھی آئے جنھیں عوام نے مردِ کامل قرار نہیں دیا تھا بلکہ انھوں نے ازخود نوٹس لیتے ہوئے اپنے آپ کو ملک پر مسلط کیا اور ان کے حاشیہ نشینوں نے انھیں مردِ کامل تسلیم کیا۔ ان میں سے ایک مردِ کامل زندہ ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد چھوٹے سے چھوٹے چینل کے چھوٹے سے چھوٹے اینکر سے ذلیل ہونے کے لیے صرف تیار ہی نہیں آرزو مند بھی رہتا ہے۔
مردِ کامل کی تشکیل میں سب سے اہم کردار خوشامد کا کلچر کرتا ہے جس کی افزائش ہمارے خطے میں خوب ہوئی ہے۔ سیاست ہی نہیں، ہر شعبے میں خوشامد کلچر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر وہ آگے نہیں نکل سکے گا وہ اپنے شعبے کے کسی بھی سرکردہ شخص کی خوشامد شروع کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کو پاکستان میں چمچا کہا جاتا تھا لیکن بڑے سائز کے چمچوں کے لیے پنجابی کا لفظ ’کُڑچھا‘ بھی استعمال ہونے لگا ہے۔
پاکستان کے کئی مردِ کامل خود بھی خوشامد ہی کے بل بوتے پر آگے بڑھے تھے، سو مردِ کامل بننے کے بعد انھیں خود بھی یہی غذا عزیز رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کو اپنی زمینوں کے آم بھجوایا کرتے تھے جس کے صلے میں انھیں پہلی مرتبہ وزارت ملی۔ اسکندر مرزا کا تختہ ایوب خان نے الٹا تو بھٹو اپنے مربی سے منھ موڑ کر ایوب خان کے ہو لیے اور ان کے ایسے مداح ہوئے کہ انھیں ’فیلڈ مارشل‘ کا رینک حاصل کرنے کا مشورہ بھی انھوں نے ہی دیا۔
فوجی افسران کمر اور گردن اکڑا کر ہاتھ ملاتے ہیں، مگر بھٹو نے فوج میں ایک ایسا افسر دیکھا جو بھٹو سے ہاتھ ملاتے وقت کمر کو رکوع کی حد تک جھکا دیتا تھا۔ بھٹو نے اسی ضیاء الحق کو چھ افسران پر ترقی دے کر آرمی چیف بنایا اور اسی نے انھیں تختہء دار تک پہنچا دیا۔
اب میں جنوبی ایشیا کے لیڈروں کی ایک اور نفسیاتی خامی کی جانب اشارہ کروں گا۔ دنیا کے ہر ملک میں بحران پیدا ہوتے ہیں اور مختلف گروہ اپنی خواہشات کو شد و مد کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ قوم میں بالغ نظر لیڈر موجود ہوں تو ان بحرانوں سے مواقع یا opportunity کا کام لیا جاتا ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں جب بھی کوئی سیاسی بحران آیا، معاملہ جذباتیت کی نذر ہو کر اور بھی گمبھیر ہو گیا۔
انیس سو چھیالیس میں کابینہ مشن منصوبے کے تحت مسلم لیگ اور کانگریس نے متحدہ ہندوستان میں رہنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی کہ معاملہ جواہر لال نہرو کے بھاشن کے شوق کی نذر ہو گیا۔ الگ ہونے کے بعد بھی دونوں ملک آپس میں شانتی سے رہ سکتے تھے، لیکن دونوں ملکوں کے لیڈروں کے طفیل باہمی مخاصمت کی فضا بڑھتی ہی چلی گئی۔
انگریزوں نے کسی بڑے خون خرابے کے بغیر صرف اور صرف مذاکرات اور بات چیت کے نتیجے میں اتنا بڑا ہندوستان چھوڑ دیا، مگر پاکستان اور بھارت کے لیڈر ہندوستان کے مقابلے میں کہیں کم رقبہ رکھنے والے علاقوں کا تصفیہ میز پر بیٹھ کر نہ کر سکے۔ کشمیر تو ایک بڑی ریاست ہے، ان رہ نماؤں سے تو سرکریک اور سیاچن کے علاقوں پر تنازعہ حل نہیں ہو پا رہا۔
اندرونِ ملک ان لیڈروں کی معاملہ فہمی کا نمونہ دیکھنا ہو تو یہاں بھی وہ ہر اہم مرحلے پر ناکام نظر آتے ہیں۔ پاکستانی لیڈر وَن مین وَن ووٹ کی بنیاد پر بنگالی رائے عامہ کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو ادھر بھارت میں اندرا گاندھی کے جی میں ایک روز آتی ہے تو وہ ملک میں ایمرجنسی لگا دیتی ہیں۔
اور تو اور شیخ مجیب الرحمان جو چوبیس برس کی جدوجہد کے بعد آزاد بنگلادیش بناتے ہیں وہ آزادی کے فوراً بعد اپنے ہاں سنگل پارٹی آمریت قائم کر دیتے ہیں۔ بنگلادیش میں حسینہ واجد کو آئین میں ترمیم کرنے جتنی اکثریت ہاتھ آتی ہے تو وہ ملک کو دوبارہ سنگل پارٹی فاشزم کی طرف لے جاتی ہیں۔ پاکستان میں سن ستتر میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان انتخابی دھاندلی کے معاملے پر مذاکرات بے نتیجہ رہتے ہیں اور ملک میں ضیائی مارشل لاء آ جاتا ہے۔
عمران خان کی صورت میں ملک کو ایک نئی امید نظر آتی ہے تو وہ چار حلقوں کی دھاندلی کی ضد لے بیٹھتا ہے اور ملکی جمہوریت کو ایک مرتبہ پھر غیر جمہوری قوتوں کی گود میں بٹھا دیتا ہے۔
ظاہر ہے ایک مردِ کامل دوسرے مردِ کامل کی بات مان جائے تو وہ خود مردِ کامل کیسے رہے؟
سوال یہ ہے کہ آخر جنوبی ایشیا کے لیڈر اپنی غلطیوں سے سیکھتے کیوں نہیں؟ وہ بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت سے کیوں محروم ہیں؟ وہ ہر مسئلے کا حل ڈنڈے کو کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ اتنے ضدی اور ہٹ دھرم کیوں ہیں؟ اقتدار میں آ کر وہ ان تمام جمہوری اصولوں کو ترک کیوں کر دیتے ہیں جن کا انھوں نے تا عمر رونا رویا ہوتا ہے؟ ان کی شخصیت میں اس جمہوریت پسندی کا فقدان کیوں نظر آتا ہے جس کا وہ دن رات ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ متعدد نفسیاتی الجھنوں میں گرفتار ان رہ نماؤں کی معاملہ فہمی کی صلاحیتیں فلاپ ہیں تو ان کی ہیرو پنتی ٹاپ پر کیوں ہے؟
ان تین ملکوں میں غیر جمہوری رویے ریسی پروکل بھی ہیں، یعنی بھارت میں انتہا پسندانہ قوم پرستی پاکستان کو ہوا بنا کر پیش کرتی ہے اور سستے نیشنل ازم سے فائدہ اٹھاتی ہے تو پاکستان میں بھارت کے مسلسل خطرے کے سبب فوج کو طاقت ور بنانے پر زور دیا جاتا ہے اور پھر یہ فوج باربار خود پاکستان کو ہی فتح کر لیتی ہے اور جمہوریت کے لیے مسلسل خطرہ بنی رہتی ہے۔ بنگلادیش کی حسینہ واجد سرکار کو بھی یہی گر ہاتھ آ گیا ہے اور وہ سیکڑوں میل دور سے آئی ایس آئی کے خطرے کا راگ الاپ کر اپنے ملک میں شخصی آزادیوں کو سلب کیے جاتی ہیں۔
جب خواب حقیقت پسندی اور وژن سے محروم ہو جائیں۔ جب ٹھنڈے دل و دماغ سے معاملے پر غور کرنے کے بجائے جذباتیت سے کام لیا جائے۔ جب اپنے حاشیہ برداروں کے کہنے پر اپنی شخصیت کو غیر معمولی، نایاب اور آسمان سے اتری ہوئی سمجھا جانے لگے تو پھر وہ فاشزم سامنے آتا ہے جس کا آج جنوبی ایشیا کی تقریباً ہر ریاست کو سامنا ہے۔
پاکستان میں چار مارشل لاء آئے اور شخصی آزادیوں پر مذیب کے نام پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ ملک مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، سو یہاں مذہب کی من پسند تعبیر کو نافذ کرنے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ کوئی اس مذہب ہی کی روشن خیال تعبیر کرتا تو اسے کافر اور غدار قرار دیا جاتا اور پھر یہ زحمت بھی ختم کر کے ان کو گولیوں اور بموں سے خاموش کرنا شروع کر دیا گیا۔ ریاستی فوج کے ساتھ ساتھ ایک رضاکار فوج بھی کھڑی کی گئی جو ریاست کو سٹریٹجک ڈیپتھ فراہم کر سکے، لیکن اس رضاکار فوج نے اپنے ہی ملک کے خون کو کسی جونک کی طرح چوسنا شروع کر دیا۔
سیکولر بھارت میں بی جے پی کو عروج حاصل ہوا، ملک میں مختلف اوقات میں ہونے والے فسادات کے ذمہ داروں کو شاید ہی کبھی سزا سنائی گئی اور بالآخر ایک ایسے صاحب وزیر اعظم بن گئے جن پر خود ایسے ہی فسادات میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ آج صورتِ حال یہ ہے کہ پاکستان کی زیادہ سے زیادہ مخالفت پر بی جے پی اور کانگریس ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔
جس ساورکر کی آخری رسومات میں بھی بھارتی حکومت کے کسی نمایاں اہل کار نے شرکت نہیں کی تھی ان کے مجسمے بنائے جا رہے ہیں اور منتخب بھارتی وزیراعظم ان کی تصویر کو پرنام کرتے ہیں۔ ایسے میں پاک بھارت دوستی کی راہ میں حائل بنیادی مسائل کے حل کے لیے نامقبول فیصلے کرنے کی ہمت دکھانے کا خواب دیوانے کا خواب ہی محسوس ہوتا ہے۔
ادھر بنگلادیش میں کئی برس کی جدوجہد کے بعد جمہوریت بحال ہوئی تو وہ دو خواتین کی لڑائی اور باہمی تو تکار کی نذر ہو گئی۔ آج حسینہ واجد ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں پھر سے ملک کی وزیراعظم ہیں جس کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تھا، لیکن وہ کسی قسم کی پشیمانی کو اپنے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتیں۔ ملک میں سنگل پارٹی کی آمریت قائم ہے اور عدالتوں سے مخالفین پر شکنجا کسنے کا کام لیا جاتا ہے۔
رونا صرف لیڈروں میں جمہوریت پسندی کے فقدان کا ہوتا تو شاید ہمارے مصائب کچھ کم ہوتے۔ لیکن پشاور سے لے کر راس کماری تک جنوبی ایشیا کے ڈیڑھ ارب لوگ بھی جمہوری تربیت سے تہی معلوم ہوتے ہیں۔ ہر معاملے پر جذباتی پہلو ان کے آگے ہوتا ہے اور منطقی پہلو پیچھے۔ ہر ملکی بحران کا حل یہ لوگ مار دو، توڑ دو، پھانسی لگا دو، باہر پھینک دو، جلا دو، گرا دو جیسے نعروں کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص سروے کر کے دیکھ لے۔
ہمارے جنوبی ایشیا کے لوگ اپنے معمول کے خاندانی معاملات کو بھی سوجھ بوجھ سے حل کرنے کی صلاحیت سے محروم نظر آئیں گے۔ ہمارے معاشروں میں چھوٹے موٹے جرائم سے لے کر قتل تک جیسے جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد یہ ثابت کرتی ہے کہ معاشرہ نچلی ترین سطح پر بھی بحرانوں کا سوجھ بوجھ سے حل تلاش کرنے میں ناکام چلا آ رہا ہے۔ ایسا معاشرہ اگر لٹھ مار قسم کے رہ نماؤں کو ہی پسند کرنے لگے تو اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے۔
عدم برداشت کا یہی رویہ ملکی سطح پر فاشزم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ فاشزم کا یہ جن پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی بوتل سے برآمد ہوا ہے تو بھارت میں یہ جن نیشنل ازم اور سستی قسم کی حب الوطنی کی چھتری تھامے اترا ہے۔
لیکن مذہبی انتہا پسندی اور اندھا نیشنل ازم دونوں یکساں خطرناک ہیں۔ یاد رکھیے کہ جرمنی میں ہٹلر نیشنل ازم کا ہی نعرہ لگاتا ہوا آیا تھا اور اسے اپنے وطن سے محبت بھی بہت تھی، لیکن جب وہ مرا تو اس کا نیشنل ازم آٹھ کروڑ چالیس لاکھ جرمنوں میں سے نوے لاکھ کی جان لے چکا تھا۔ اپنی قوم کی حالت سدھارنے کے لیے اسے یک جا کرنا، اس کی معیشت، اس کی سماجی حالت بہتر بنانے کے لیے کام کرنا اور اس کے لیے اپنی ہی قومی تاریخ سے مثالیں نکال کر لانا بہت خوش آیند ہے۔
لیکن یہ کہنا کہ دنیا میں بھارت ماتا جیسی کوئی دھرتی ہی نہیں اتنا ہی خطرناک ہے جتنا جرمن نازیوں کا یہ کہنا کہ جرمن قوم اور آریائی نسل دنیا کی بہترین نسل ہے یا انتہا پسند مسلمانوں کا یہ کہنا کہ مسلمان خدا کی پسندیدہ قوم ہیں۔ یہ ایک نئی دنیا ہے جس کے نوجوان دن بدن ایک مشترک کلچر سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اپنے کلچر کے تحفظ کا خواب دیکھنا اور دکھانا بہت خوب، لیکن خیال رہے کہ فاشزم کے راستے بھی اسی خواب سے نکلتے ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ جمہوریت کے نام کی مالا جپنے کے بجائے اس کے زریں اصولوں کو اپنے دل و دماغ میں اور پھر ان عوام کے دل و دماغ میں راسخ کیا جائے جنھوں نے اس جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے۔ جمہوریت ہمیں ایک ایسے معاشرے نے دی ہے جو چیزوں کی تفصیلات جمع کر کے ان کا تجزیہ کرنے پر یقین رکھتا ہے، جس نے یہ جان لیا ہے کہ جمہوریت میں حکومت تو اکثریت کی ہوتی ہے مگر لسانی، نسلی اور مذہبی اقلیتوں کا بڑے پیار سے خیال رکھا جاتا ہے۔
لیکن نرگسیت کے مریضوں میں ایسا وژن کہاں سے آئے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے رہ نما جمہوریت اور اس کے لوازمات سے اپنی وابستگی کے دعوے جتنے مرضی کرتے ہوں مگر وہ انھیں اپنے اعتقادات، اپنے خون، اپنی روح کا حصہ نہیں بنا سکے۔ کسی بھی بحران کے موقع پر ان کے شخصی تعصبات ان پر حاوی آ جاتے ہیں اور وہ غیر جانب داری اور انصاف پسندی سے کسی معاملے کا تصفیہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ثابت ہوتے ہیں۔
عربی کی مشہور کہاوت ہے کہ عوام اپنے بادشاہوں ہی کے مذہب پر عامل ہوتے ہیں۔ اس کہاوت کو الٹ کر دیکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے حکم ران بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے ہمارے عوام ہیں۔ انفرادی اور معاشرتی سطح پر عدم برداشت کا رویہ ہی ملکی سطح پر فاشزم کی شکل اختیار کرتا ہے۔ مگر برصغیر میں بڑھتے ہوئے فاشزم کا حل کیا ہے؟ اکثر لوگ حل یہ بتاتے ہیں کہ معاشرے میں تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ مگر جب میں برصغیر کے تعلیم یافتہ زید حامدوں اور ارنب گوسوامیوں کو دیکھتا ہوں تو اس حل پر سے بھی میرا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔
میرا تو یہ خیال ہے کہ قوموں اور معاشروں کا مجموعی مزاج تبدیل کرنے میں کئی صدیاں لگتی ہیں۔ مغرب کے رہ نما جو آج ہمیں تدبر اور فراست سے مالامال نظر آتے ہیں تو اس کے پیچھے یورپ کی کئی خونیں صدیوں کا تجربہ بھی ہے۔ مگر کیا ہم بھی بہت سا کشت و خون دیکھنے کے بعد ہی سدھر سکیں گے؟ وہ تاریخ سے جو سبق سیکھ چکے، کیا ہمیں وہی سبق سیکھنے کے لیے ویسے ہی تجربات سے گزرنا ہوگا؟ نہرو اپنی بیٹی اندرا گاندھی کو جیل سے خطوط لکھ کر عالمی تاریخ سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ ان کی بیٹی امن کی فاختہ نہ بن سکیں۔ تاریخ کے علم کا انھوں نے یہ فائدہ ضرور اٹھایا کہ اپنے ایٹم بم کا نام گوتم بدھ کے نام پر رکھ گئیں۔
فی الحال تو ہماری تعلیم ہم سے یہی کچھ کرا سکتی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ برصغیر کے دو بڑے ملکوں کے پاس ایٹمی صلاحیت آنے کے بعد ان کے معاشروں میں فاشسٹ رویے اور بھی خطرناک ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ہمارے ڈیڑھ ارب عوام ایک ایسے بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں جو کسی بھی وقت بھک سے اڑ سکتا ہے۔ جن معاملات اور مسائل کو حل کرنے میں ہمارے بانیان بھی ناکام رہے، انھیں حل کیے بغیر چھوڑ دینے سے وہ اور بھی پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ کیا ایسے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے دل میں امید کی شمع کو جگائے رکھیں؟
تقسیمِ ہند کے بعد سڑستھ برس بعد بھی برصغیر کے تین بڑے ملکوں کے عوام کئی اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ ممبئی کی کسی فلم میں کوئی نیا اور عوامی فقرہ سننے کو ملتا ہے تو یاد آتا ہے کہ یہ فقرہ تو کراچی کی سڑکوں پر سنا تھا۔ انٹرنیٹ سے دلچسپی رکھنے والی نئی نسل کی آرزوئیں، امنگیں اور جذبات بھی ایک سے ہیں۔ لیکن اپنی زندگی کے ہیرو ہیروئن ان نوجوانوں میں اس سنجیدگی کی کمی ہے جو تقسیمِ ہند کے زمانے کے دلیپ کمار اور نرگس میں نظر آتی تھی۔
ڈیٹنگ، پارٹی، فیس بک، سیلفی اور ٹوئٹر کی دنیا میں گھومتے، زندگی کو انجوائے کرنے کے شوقین ان لڑکے لڑکیوں کو جب ذرا سا کریدا جاتا ہے تو ان میں ایسا نیشنل ازم اور مذہب پسندی دکھائی دیتی ہے جسے ممبئی کی ایک فلم ’حیدر‘ کے مرکزی کردار کے الفاظ میں ’چُٹس پا‘ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے ڈیڑھ ارب عوام بارود کے ڈھیر پر نہ بیٹھے ہوتے تو شاید ہم اس چُٹس پا کو ہنسی میں اڑا سکتے۔
پچھلے چند برسوں کے دوران کم از کم بھارت اور پاکستان میں سول سوسائٹی بھی بہت مضبوط ہوئی ہے جو اپنے مزاج میں سیکولر ہے اور جمہوریت کے لوازمات پر یقین بھی رکھتی ہے۔ اس سول سوسائٹی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی آؤٹ لک میں میڈ ان پاکستان اور میڈ ان انڈیا نہیں لگتی۔ اسی لیے پاک و ہند کے عام افراد انھیں اجنبی خیال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے معاشرے کے غریبوں اور پچھڑے ہوئے طبقے سے رابطہ استوار کر سکیں تو امید کی شمع روشن کی جا سکتی ہے۔
اور امید کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں۔ ن م راشد کی نظم ’حسن کوزہ گر‘ کے یہ مصرعے امید کی انھی شمعوں کی نذر:
جہاں زاد بازار میں صبح عطار یوسف
کی دکان پر تیری آنکھیں
پھر اک بار کچھ کہہ گئی ہیں
ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تودہ خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش
یہی شاید اس خاک کو گِل بنا دے
نوٹ: سید کاشف رضا کا یہ مضمون اس سے پہلے ادبی دنیا پر شائع ہو چکا ہے۔