
عابد سیال
گذشتہ تقریباً ڈھائی عشروں سے اردو غزل کا مسلسل اور بزعمِ خود دردمند قاری ہونے کے ناطے میں مدت سے معاصر غزل کے بارے میں وقتاً فوقتاً جاری ہونے والے موافق و مخالف فرامین کی روشنی میں اس ’خوش نصیب‘ صنفِ شعر کی رسائیوں اور نارسائیوں پر سوچتا رہتا ہوں۔ اس دردمندی کی ایک وجہ کی سرحدیں توخودغرضی سے جا ملتی ہیں کیونکہ ادب کے میدان میں داخلے کے لیے میں نے شاعری کا ٹکٹ استعمال کیا ہے جو زیادہ تر غزل ہی کی ہیئت میں ہے۔ اور اگر میرا کوئی ادبی مستقبل ہے تو بیشتر امکان اسی بات کا ہے کہ وہ اسی صنفِ سخن سے جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا غزل کے مستقبل کی فکر کرنے کا مطلب میں اپنے طور پر اپنے مستقبل کی فکر کرنا سمجھ کر یہ روگ پالے ہوئے ہوں۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی صنفِ سخن جس میں ہمارے اب تک کے شعری ادب کا وقیع ترین سرمایہ محفوظ ہے، چلچلاتی دھوپوں اور چنگھاڑتی آندھیوں سے گزر کر بھی اپنا آپ بچا لائی ہے تو ڈارون والے سائنسی نہ سہی کسی ادبی قانونِ ارتقا و بقا کی روشنی میں اس کی بقا کے مظہر کو کسی تہذیبی، ثقافتی یا لسانی زاویے سے دیکھنے پرکھنے کی ضرورت نظر آتی ہے۔ تیسری وجہ جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے، یہ ہے کہ مجھے اپنے طور پر یوں لگتا ہے کہ اکیسویں صدی میں شاعری کو شعار کرنے والے نئے لوگوں میں نہ صرف تعداد کے اعتبار سے غزل سے اعتنا کرنے والے زیادہ ہیں بلکہ پچھلے دو عشروں میں سامنے آنے والے جن شاعروں کے ہاں تازگی اور ندرت کا احساس نمایاں ہے، ان میں زیادہ تر غزل کہنے والے ہیں۔
اگر اسے بے ادبی (بہ معنی ادب نافہمی) نہ سمجھا جائے تو سہما سہما ایک خیال میرے دل میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں غزل نے معروف معنی میں ’روایتی‘ ہونے میں تین چار صدیوں کا وقت لیا، نظم کی بیشتر شاعری نے نظم کے خاص حوالوں سے اس طرح کے ’روایتی‘ مقام پر پہنچنے میں ایک صدی سے بھی کم وقت لیا ہے۔ خیر اس آخری بات کو تو ایک جملۂ معترضہ سمجھ کر فی الحال ایک طرف کیا جا سکتا ہے، بات یہ ہو رہی تھی کہ میں چند وجوہ کی بنا پر غزل کی شاعری کو خاص طور پڑھتا ہوں۔اب اگر یہ مفروضے درست ہیں، اور نیا شاعر کسی بھی وجہ سے غزل کو ترجیحی ذریعۂ اظہار کے طور پر اختیار کر رہا ہے تواس کے موجودہ stuff کی رسائیوں اور نارسائیوں پر مسلسل بات ہونی چاہیے تاکہ تازگی اور تازگی کے التباس؛ پختگی اور پختگی کے وہم ؛اور ہنر اور کاریگری میں امتیاز کرتے ہوئے ’اصل شاعری‘ کو پہچانا اور سراہا جائے۔ تاکہ روشِ عام سے بچ کر غزل کہنے والوں کی شناخت مستحکم کرنے کی طرف پیش رفت ہو سکے۔
معاصر غزل کے جاری سفر کے اب تک کے حاصلات اور امکانات پر بھی تواتر سے بات ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلکہ کسی قدر زیادہ توجہ سے اس کی نارسائیوں کو پہچاننے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے ۔اس ضمن میں پہلی بات مصرعے کی تراش پر ہے۔سو یہ تحریر اسی ایک نکتے پر مرتکز ہے۔
معاصر غزل میں مصرعے کی تراش میں جو خصوصیت اب حیرت انگیز حد تک عام ہو گئی ہے، وہ اس کا ایک حد تک چست اور پختہ ہونا ہے۔ چار پانچ دہائیاں پہلے تک کے شعرا میں مصرعے کی جو تراش ایک خاص عمر تک ریاضت کرنے کے بعد آتی تھی کہ مصرعے کا آغاز کس طرح کے لفظ سے ہو، اختتام کیساہو، اس میں لفظوں کی نشست کیسی ہو، اب تھوڑی تھوڑی عمر کے شاعروں کے ہاں ایسے مصرعے فراوانی سے ملتے ہیں۔ وہ ’الف‘ ، ’ی‘ یا ’ے‘ پر ختم ہونے والے حروف جار کو کھلے قافیوں کے طور پر استعمال کر کے بہ افراط چونکانے والے مصرعے بنا لیتے ہیں جو ایک زمانے میں پختہ کار شاعروں کے ہاں ہنرکاری کا نمونہ سمجھے جاتے تھے۔ وہ اس بے ساختگی سے صرفِ ردیف کرتے ہیں کہ سامع یا قاری کو تیغِ ہنر سے گھائل ہونے کا احساس اس کے وار کے کافی دیر کے بعد ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ وار گہرا بھی ہوتاہے۔ یا اسی طرح کے دیگر حربوں یا صورتوں سے معاصر شعرا کی ایک قابلِ لحاظ تعداد کامیابی اور فراوانی سے ایسے مصرعے تخلیق کر رہی ہے جو پہلی قرأت یا پہلی سماعت میں قاری یا سامع کو درِ حیرت پر لا کھڑا کرتے ہیں جس کا فوری تاثر ظاہر ہے کہ بہت خوشگوار ہوتا ہے۔
قاری کو فن کی حیرت میں مبتلا کر دینا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے جس سے قاری تخلیق کے جہانِ معنی کی وسعت اور گہرائی میں داخل ہونے پر مائل ہوتا ہے۔لیکن مسائل کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد اندر بھی کچھ موجود ہے یا نہیں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ ترصورتوں میں معاملہ بڑے شہروں کے مضافات میں جابجا اُگنے والی ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں جیسا ہے جن کے بڑے بڑے اور شاندار گیٹ اور بُرج ہیں جن پر پہرے دار اور آرائشِ گل ایسی ہے ، گویا اندر شہرآباد ہے۔ لیکن گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی تاحدِنظر اجاڑ چٹیل میدان،نہ مکین نہ مکان۔ اور اگر کہیں راستے موجود ہیں تو منزل ناپید۔ کسی زمانے میں شہر پہلے بستا تھا، پھر اس کی حفاظت کی فکر ہوتی تھی تو فصیل اور دروازہ اور پھر اس کی آرائش کی فکر ہوتی تھی تو آرائشی تعمیرات کی جاتی تھیں۔ اب فصیلیں، دروازے اور آرائش پہلے اور مکینوں کی تلاش اور مکانوں کی استواری بعد میں کی جاتی ہے۔
بات چونکہ غزل پر ہے اور وہ بھی معاصر غزل پر تو باقی اصنافِ ادب کی بات چھوڑتے ہوئے صرف غزل کو دیکھیں تو اس کی بیشتر صورت حال بھی جدید دور کے اسی رجحان کے موافق ہے کہ بظاہر عمدہ نظر آنے والی شاعری کے فن کے ظاہری دروازے اونچے اور بارعب مگر اندرون خالی ہے۔ بیان کم اور زورِ بیان زیادہ ہے۔ پختہ اور چست مصرعوں کے پیچھے وہ رنگ رس ، گداز ، تہ داری اور کیفیت نہیں جو بطور صنف، غزل کا خاصہ اور امتیاز ہے۔ اس شاعری کا مافیہ (content) زیادہ تر روایتی ہے (کلاسیکی نہیں روایتی)۔ انفس و آفاق، زمان و مکاں، مابعدالطبیعیات و الٰہیات، جذب و عشق، رندی و مستی، ربط و ضبط، شعور و دانش اور دیگر وہی مضامین جن کی کیفیات غزل کی شاعری میں راسخ ہو چکی ہیں، ذرا سی بدلی ہوئی صورت میں، کسی قدر مختلف ڈھنگ سے، اِس زمین کا قافیہ اُس زمین میں لگا کر ، ردیف کا صیغہ بدل کر، اسی ردیف و قافیے کو کسی اور بحر میں ڈھال کر، بحر کے ارکان میں توسیع و تخفیف کر کے یا دیگر ذرائع سے شاعری کو نیا کرنے کا التباس پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال بذاتِ خود کوئی قابلِ مذمت چیز نہیں ہیں کیونکہ غزل کی صنف میں گنجائشیں اور اجازتیں اسی نوع کی ہیں، تقاضا دراصل یہ ہے کہ فکر و معنی کے روایتی سرمائے کے کچھ نئے زاویے یا اپنے عہد اور اس کی حسیت سے جڑے ہوئے نئے فکری منطقے تخلیق یا تلاش کیے جائیں اور پھر ان کے نئے ہونے کے جواز کے ساتھ مصرعوں میں ایسی ظاہری تبدیلیاں لائی جائیں جو اس فکر سے ہم آہنگ ہوں۔ فکر اور فن یوں باہم پیوست ہوں کہ ہنر کا مطلب صرف فنی حربوں اور کاری گری تک محدود نہ رہے بلکہ حرف و معنی کے ارتباط سے ایسی شعری تخلیق سامنے آئے جس کے روح و جسم تازگی کا احساس دلاتے ہوں۔
آخر آخر تک آتے آتے بات کچھ زیادہ مثالیت کی طرف چلی گئی ہے۔ تاہم ایسی مثالی صورت تک نہ بھی پہنچا جا سکے تو ایک خاص فنی ریاضت تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ یا کم از کم پہنچنے کے بعد غزل کے شاعر کو سرکس کے کھلاڑیوں کی طرح یا کسی سٹیج ڈرامے میں ایک نہایت عمدہ اور فطری اداکاری ادا کرنے والے فنکار کی طرح بار بار انھی کرتبوں، شعبدوں اور اداکاری سے اپنے پڑھنے والوں کو خوش کرنے کی بجائے اس ہنر کو انھیں اپنے ساتھ ساتھ رکھنے کے وسیلے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے اور انھیں کشاں کشاں کسی نئے جہانِ معنی کی طرف لے جانا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا اسی صورت میں ممکن ہے جب خود شاعر کی رسائی کسی ایسے جہان تک ہو چکی ہو۔اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ اس کی فکر میں مبتلا نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ جس قدر اور جس نوع کی محنت، ریاضت اور قصد فنی حربوں کو سیکھنے اور ان کے استعمال میں بے ساختگی اور ملائمت لانے میں درکار ہے، اسی طرح کی کاوش معنی کی اختراع میں بھی درکار ہے۔ ’معنی کا اختراع‘ شاید عجیب لگے۔ لیکن میرے خیال میں سامنے کی باتوں، اردگرد کے مسائل ، نفسیاتی کشمکشوں، جذباتی فشار اور دیگر انسانی کیفیات کو جھاڑ جھنکار الگ کر کے کسی قدر کاوش کے ساتھ شعری مواد میں ڈھالنا پڑتا ہے جو بعد ازاں ازخود شعورولاشعور کا حصہ بنتا ہے اور تخلیق کے پراسرار عمل سے گزر کر نئے اور تازہ روپ میں سامنے آتا ہے۔ ایک خاص حد تک فنی ریاضت تک پہنچے ہوئے شاعر کو معنی کے اختراع کی فکر بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کا کہا ہوا نیا ہو، نئے کا التباس نہ ہو۔


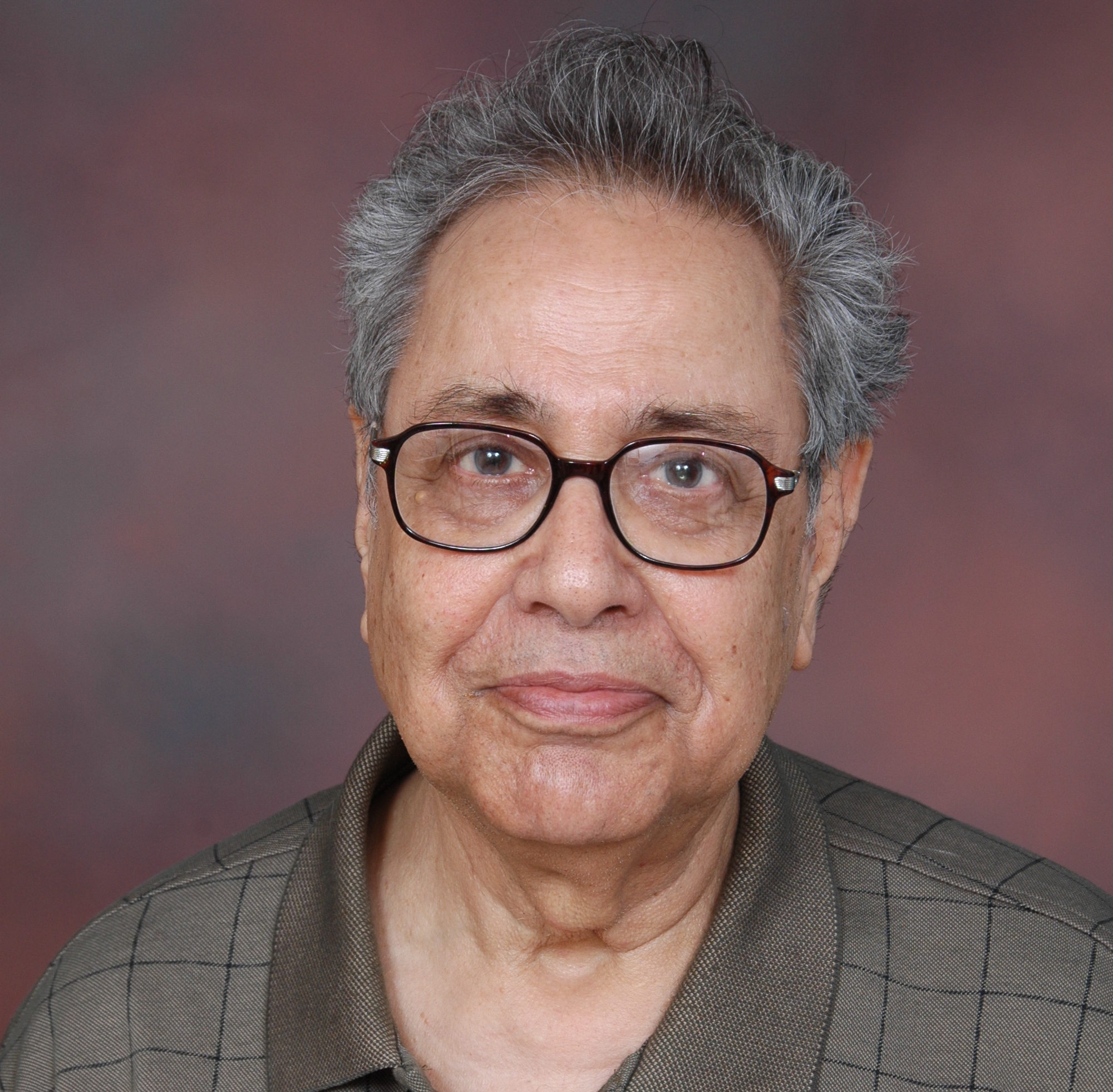


عمدہ مضمون ہے . اسی رجحان کو ایک جگہ میں نے گویوں کی غزل کے نام سے معنون کیا تھا . شاعری اعلٰی خیال کے بنا تھوتھا چنا بھر ہی ہے .